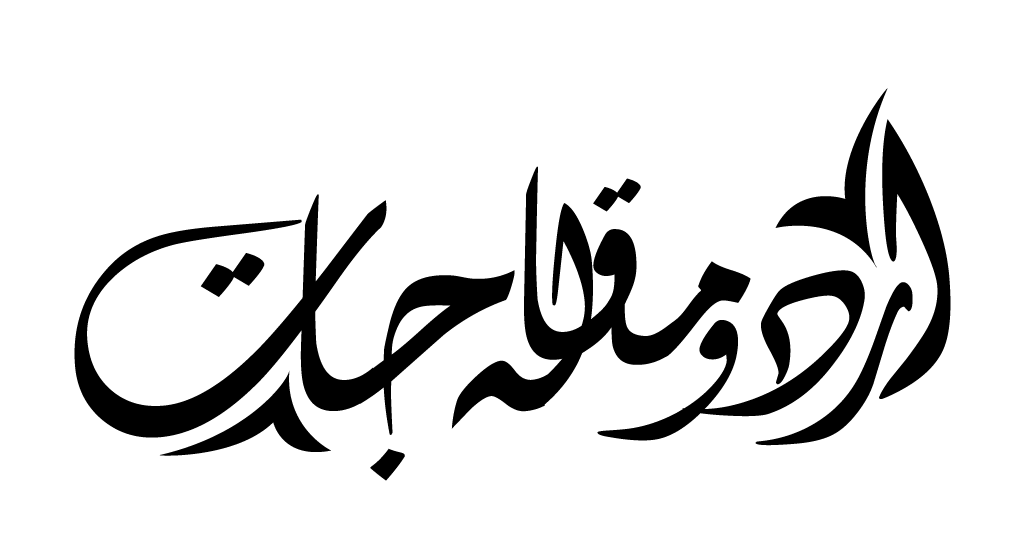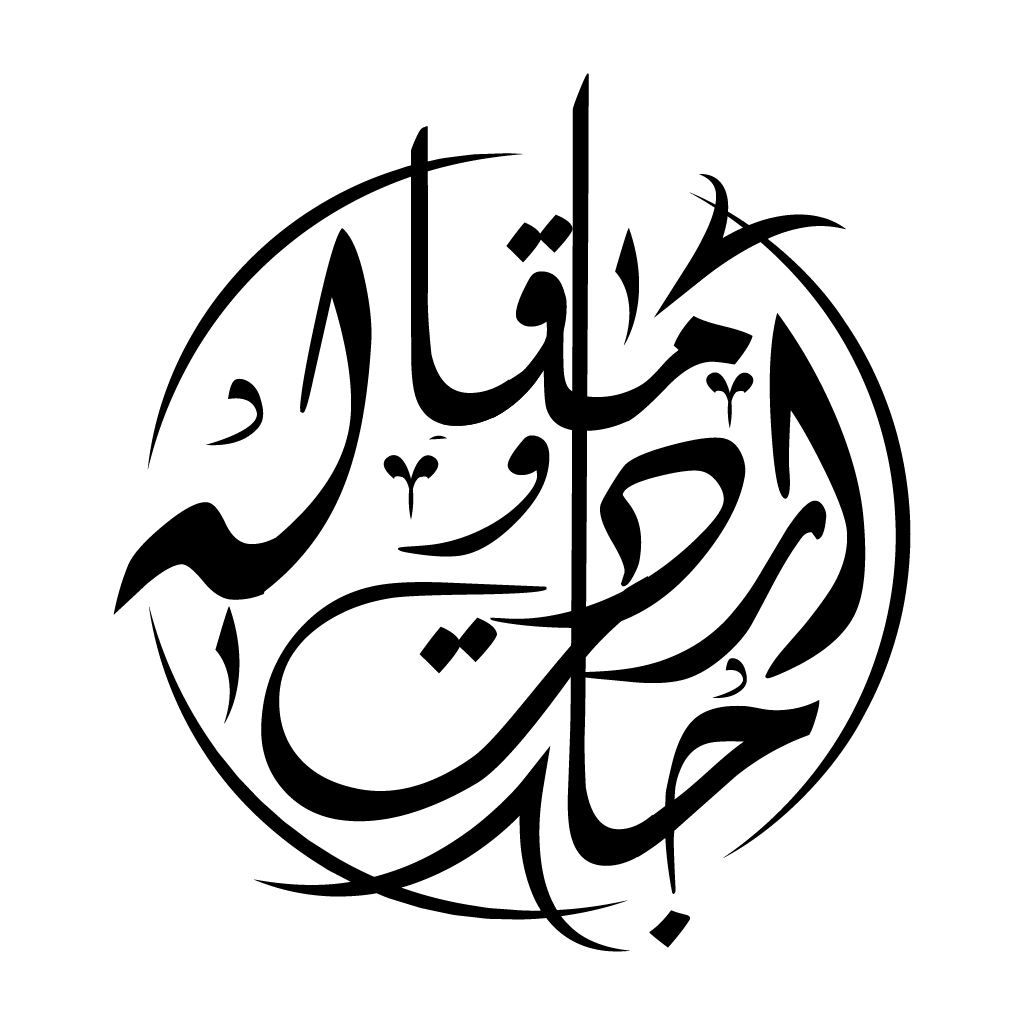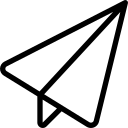اقبال کا شعری سرمایہ ہمارے پاس زیادہ تر باقاعدہ مدوّن مجموعوں (بانگِ درا، بالِ جبریل، ضربِ کلیم، ارمغانِ حجاز) اور فارسی دواوین (اسرارِ خودی، رموزِ بے خودی، مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوامِ شرق، پیامِ مشرق، زبورِ عجم، جاوید نامہ، لزومیاتِ اقبال وغیرہ) کی شکل میں موجود ہے؛ مگر اس کے ساتھ وہ متن بھی کم اہم نہیں جو ان مجموعوں کے باہر بچا رہ گیا—خاکہ بند اشعار، متروک اور حذف شدہ مصرعے، اوّلین رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی ایسی صورتیں جو بعد میں اقبال نے خود بدل دیں، خطوط و ڈائری نوٹوں میں بکھرے مصرعے، یا وہ کلام جو مختلف اسباب سے کلیات میں ضم نہیں ہو سکا۔ اسی مجموعی متنی پیکر کو تنقیدی روایت میں ’’باقیاتِ شعرِ اقبال‘‘ کہا جاتا ہے۔ ان باقیات کا مطالعہ دو سطحوں پر بیک وقت اہم ہے: (۱) متنی تنقید و تدوینِ متن کے نقطۂ نظر سے تاکہ اقبال کے حتمی متن تک پہنچنے کے عمل (genetic process) اور متن کے اندر وقوع پذیر نقل و حرکت (textual mobility) کو سمجھا جا سکے؛ (۲) فکری و شعری ارتقا کے زاویے سے تاکہ یہ واضح ہو کہ اقبال نے کن اسباب کے تحت بعض اشعار کو رد، تبدیل یا مختصر کیا، اور ان فیصلوں نے ان کے فکری نظام—خصوصاً خودی، ملت، نیابتِ الٰہی، عشق و عقل کی جدلیات، اور حریتِ فکر—کی تشکیل میں کیا کردار ادا کیا۔
اقبال کے بہت سے اشعار پہلے پہل مخزن، زمانہ، ہمایوں، اور بعض دیگر رسائل میں شائع ہوئے۔ بعد ازاں جب وہ بانگِ درا یا دیگر کلیات میں شامل ہوئے تو کئی جگہ قرأت بدل گئی، الفاظ و تراکیب میں ترمیم ہوئی یا پورے پورے اشعار حذف ہو گئے۔ باقیات کے اہم حصے کی بازیافت اسی اوّلین صحافتی مواد اور مسودہ نویسی کے سراغ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض نظموں میں ایسے مصرعے ملتے ہیں جن میں سیاسی شدت، استعمار مخالف صراحت یا داخلی خوداحتسابی کا لہجہ نسبتاً تند تھا، مگر بعد میں اقبال نے انہیں نرم تر استعارہ یا زیادہ جامع تمثیل میں منتقل کر دیا۔ متنی محققین نے اس فرق کو محض لفظی نہیں، فکری ارتقا کے طور پر بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے—یعنی اقبال نے تدریجاً اپنی شعری زبان کو زیادہ آفاقی اور کثیرالمعنی بنانے کی طرف قدم بڑھایا، اور جہاں کہیں فوری سیاسی ناروا خشتبےمحل محسوس ہوئی اسے استعارہ اور ارفع اخلاقی اشاریت سے بدل دیا۔
اس زاویے سے باقیاں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ اقبال کی ’’حذف‘‘ کی حکمتِ عملی کیا تھی: کیا وہ داخلی فنی کمال کی جستجو تھی، سیاقی و زمانی دباؤ، سامع/قارئہ کی نفسیات کا لحاظ، یا کسی وسیع تر فکری ارتقا کا اظہار؟ مثال کے طور پر ’’شکوہ‘‘ اور ’’جوابِ شکوہ‘‘ کی پہلی اشاعتوں اور کلیات کی شکل کے مابین لسانی اور آئڈیائی فرق بالکل کم ہے، مگر بعض حاشیے اور تعارفی جملے جو رسائل میں ملتے ہیں، کلیات میں غائب ہیں—یہ غیاب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اقبال اپنے متن کو خطیبانہ جواز سے اٹھا کر محض شعری و وحیانی لہجے کی سطح تک لے جانا چاہتے تھے۔
ادبی متون کے اوّلین مسودات، حواشی، حاشیہ نویسی، بین السطور تبدیلیاں اور قلمی نسخے ’’جینیاتی تنقید‘‘ کے مواد سمجھے جاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں یہ مواد پوری طرح محفوظ نہیں رہا، مگر خطوط، ڈائری نوٹس، دوستوں (غلام رسول مہر، شیخ عبدالقادر، سید سلیمان ندوی، نیاز فتح پوری) کو بھیجے گئے مسودات، اور مجلّات میں چھپنے والی اوّلین صورتیں اس کمی کی کسی حد تک تلافی کرتی ہیں۔ باقیاں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ایک نظم یا غزل اپنی حتمی صورت سے پہلے کن معنوی و اسلوبی حالتوں سے گزری۔ مثال کے طور پر فارسی کلام میں بعض جگہ عروضی بندشوں کی دلیل سے الفاظ بدلنا پڑے، لیکن اردو میں شعوری طور پر ’’ثقالت‘‘ سے ’’صفائی‘‘ کی طرف تبدیلی زیادہ واضح ہے—یہ تبدیلیاں اقبال کی مسلسل خودترمیمی(self-editing) ذہن کی عکاس ہیں۔
اقبال کے فکری نظام میں چند مرکزی مفاہیم ہیں: خودی، مردِ مومن، عشق، عقل، نیابت، حریت، اجتہاد، ملت، تہذیبی احیا، اور زمان و مکان کی نئی قرأت۔ باقیات میں جب ہم حذف و اضافہ کی مثالیں دیکھتے ہیں تو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال جب کسی تصور کو زیادہ دقیق، زیادہ کلی اور کم سطحی یا وقتی بنانا چاہتے تھے تو وہ بعض حاشیائی اشعار کو نکال دیتے—یوں حتمی متن میں فکر کی ’’معماری‘‘ مضبوط اور واضح تر ہو جاتی ہے۔ مثالاً ابتدا کے عشقیہ رنگ یا محض رومانوی کیفیت کے حامل کچھ اشعار کلیات میں جگہ نہیں پاتے، کیونکہ وہ بعد کے اقبال کے بڑے فکری بیانیے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہتے۔ یوں باقیاں ہمیں ’’ایک مسلسل فکری editing‘‘ کی داستان سناتی ہیں، جس کے تحت شاعر اپنے ماضی کے بعض بیانات کو وسیع تر نظام کے حق میں قربان کرتا ہے۔
باقیات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان میں ہمیں اقبال کے زبان سے تجربوں کا وہ حصّہ ملتا ہے جو حتمی سنوار تک نہیں پہنچا۔ کہیں فارسی تراکیب کی کثافت ہے، کہیں مقامی محاورہ اپنی شدّت کے ساتھ آ کر مرکزی بیانیے سے ٹکرا جاتا ہے، کہیں صوتیاتی سطح پر وزن و بحر کی ایسی گرفت موجود ہے جسے بعد میں شاعر نے ڈھیلا کر دیا تاکہ مفہوم کی روانی برقرار رہے۔ اقبال کی اردو نعتیہ شاعری، ملیاتی بیانیے اور سیاسی مزاج کی نظموں میں جو دروبست (architecture) ہمیں کلیات میں ملاوٹ و امتزاج کی صورت میں ملتا ہے، اس کی خام اور غیر صیقل شکل باقیاں فراہم کرتی ہیں—یوں ان نصوص کا مطالعہ اقبال کی ’workshop‘ میں جھانکنے کے مترادف ہے۔
1857 کے بعد کا نوآبادیاتی سیاق، برصغیر کی مسلم سیاست، نیچریت و جدیدیت کے مباحث، خلافت کی تحریک، برطانوی سامراج کے خلاف فکری مزاحمت، اور بعد ازاں مسلم ملی ریاست کے امکان—یہ تمام عوامل اقبال کی شعری زیست کی بنیاد ہیں۔ باقیات میں کئی مقامات پر ایسے اشارات ملتے ہیں جن میں اقبال کا لہجہ زیادہ براہِ راست سیاسی، یا زیادہ مذہبی-اصلاحی ہے؛ مگر حتمی متن میں یہی عناصر استعاراتی، قرآنیاتی اور فلسفیانہ اصطلاحات کے پردوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیلی کو محض self-censorship کہنا درست نہیں؛ زیادہ معقول بات یہ لگتی ہے کہ اقبال نے اپنے بیانیے کو ’’مابعد العارض‘‘ سطح پر اٹھانے کی کوشش کی—یعنی عارضی سیاسی تقاضوں کو ایک دائمی فکری ڈھانچے میں ضم کرنا۔ باقیات ہمیں ان ’’عارضی لہجوں‘‘ کے سراغ دیتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ شاعر اپنے سیاق سے کیسے اوپر اٹھ کر ایک آفاقی خطاب کی سمت گیا۔
اقبال کے متن پر ’’تقدیس‘‘ کا غلبہ ایک ادبی-تنقیدی مسئلہ بھی ہے۔ جب شاعر کو قومی، تہذیبی اور فکری سطح پر ’’علامت‘‘ کا درجہ مل جائے تو اس کے متن پر ’’تنقیدی دسترس‘‘ مشکل ہو جاتی ہے۔ باقیاں اس حوالے سے اہم ہیں کہ وہ اقبال کے ’’انسانی‘‘ اور ’’کام کرتے شاعر‘‘ ہونے کا ثبوت دیتی ہیں—ایک ایسا شاعر جو غلطی بھی کرتا ہے، خود کو بدلتا ہے، فکری طور پر پختہ ہونے کے مراحل سے گزرتا ہے، اور اپنی عبارت کو تراشتا رہتا ہے۔ باقیاں اس تقدیس کو بے ادبی کے معنی میں نہیں بلکہ فنی و فکری حقیقت کے طور پر چیلنج کرتی ہیں: ایک عظیم متن کے پیچھے ہمیشہ ایک عظیم اور مسلسل عملِ تخلیق ہوتا ہے، جس میں رد و قبول کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔
آج جب عالمی سطح پر متون کے ’’ڈیجیٹل کرٹیکل ایڈیشنز‘‘ (Digital Critical Editions) تیار ہو رہے ہیں، اقبال کے کلام کے لیے بھی ایسی ہی ایک کوشش کی ضرورت شدید ہے جس میں ہر نظم/غزل کی تمام دستیاب قراآت، رسائل میں چھپی صورتیں، خطوط میں مذکور تبدیلیاں اور محققین کے نوٹس شامل ہوں، ساتھ ہی ہر تبدیلی کی وجہ (جہاں تک ممکن ہو) حاشیے میں درج کی جائے۔ اس سے نہ صرف اقبال کا حتمی متن مزید مضبوط ہو گا بلکہ اقبالیات کے طلبہ اور محققین کو شاعر کے فکری و فنی سفر کی ’’ریل ٹائم‘‘ جھلک ملے گی۔ باقیاں اس ڈیجیٹل ایڈیشن کی ریڑھ کی ہڈی کا کام دے سکتی ہیں۔
اقبال کی شاعری محض سیاسی/اخلاقی نظموں کا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ ایک ’’وجودی جدوجہد‘‘ بھی ہے۔ باقیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ کیسے بعض جگہ شاعر نے وجود، روح، تقدیر، جبر و اختیار، عقل و عشق کی کشمکش کو مختلف الفاظ میں پرکھا اور پھر ان میں سے کسی ایک بیانیے کو منتخب کیا۔ بعض مقامات پر وہ اپنے شعلہ فگن لہجے سے دست بردار ہو کر ایک صوفیانہ سکوت کی طرف جاتے ہیں، یا محض خطابت کو چھوڑ کر خودی کے باطنی ارتقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سب ترمیمی آثار بتاتے ہیں کہ اقبال کے ہاں فکر محض ’’posture‘‘ نہیں بلکہ ’’process‘‘ تھی—اور یہی ان کی شعری عظمت ہے۔
تحقیقی سہولت کے لیے باقیاں کم از کم چار خانوں میں رکھی جا سکتی ہیں:
- اوّلین مطبوعات میں اختلافی قراآت: وہ اشعار/نظمیں جن کی ابتدائی اشاعت اور حتمی کلیات میں لفظی/اسلوبی فرق ہے۔
- حذف شدہ/متروک کلام: وہ اشعار جو بعد میں کلیات میں شامل ہی نہیں ہوئے یا بہت ترمیم کے ساتھ آئے۔
- خطوط و ڈائری کے موزوں مصرعے: وہ اشارات جو اشعار کی تخلیق کے دوران یا بعد میں لکھے گئے اور باقاعدہ نظم/غزل میں ضم نہ ہو سکے۔
- ’’فکری حاشیے‘‘ اور تعارفی نوٹس: وہ نثری بیانات جو نظموں کے پس منظر، مقصد یا مفہوم کی توضیح کرتے ہیں، مگر کلیات میں حذف ہو گئے۔
ایسی فہرست مرتب ہو تو اقبال کے ’’جینیاتی‘‘ (genetic) شعری سفر پر ایک نیا باب لکھا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف ان کی متن شناسی مضبوط ہوگی بلکہ فکر کی ارتقائی تاویل بھی واضح ہوتی جائے گی۔
باقیاتِ شعرِ اقبال کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ہمیں دو بڑے نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اول، اقبال ایک ہمہ وقت ’’نظرِ ثانی‘‘ کرنے والے شاعر تھے—ان کے ہاں متن کی تقدیس سے زیادہ فکر کی صحت اور اسلوب کی شفافیت اہم تھی۔ اسی لیے وہ اپنے ہی لکھے ہوئے پر دوبارہ ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے نہیں۔ دوم، ان باقیات کے مطالعے سے اقبال کی شعری و فکری تشکیل کے وہ درمیانی پُل سامنے آتے ہیں جو عام طور پر مدوّن کلیات میں غائب ہو جاتے ہیں؛ اور یہ پُل ہمیں بتاتے ہیں کہ اقبال نے کس طرح وقتی سیاسی بیان سے دائمی تہذیبی و ایمانی بیانیے کی طرف سفر کیا، اور کس طرح ذاتی واردات سے اجتماعی خودی تک پہنچے۔ اقبال کے باقیات دراصل اُن کے ’’بیک اسٹیج‘‘ کا منظرنامہ ہیں: وہاں جہاں ایک بڑا شاعر اپنے الفاظ سے کشتی لڑتا ہے، اپنے لہجے کو تولتا ہے، اپنی فکر کو ناپتا ہے، اور پھر ایک جامع اور آفاقی متن کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبالیات کی آئندہ سنجیدہ تحقیق میں باقیات کو حاشیے سے اٹھا کر مرکز میں لانا، اور ایک باقاعدہ تنقیدی-ڈیجیٹل ایڈیشن کی صورت میں محفوظ کرنا نہ صرف علمی ضرورت ہے بلکہ اقبال کے ساتھ ایک دیانت دارانہ ادبی سلوک بھی۔