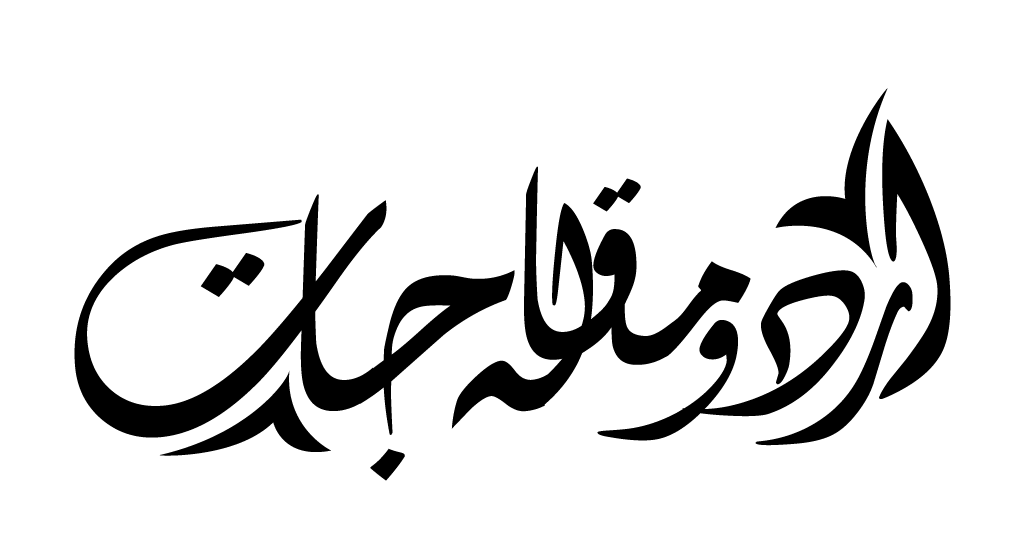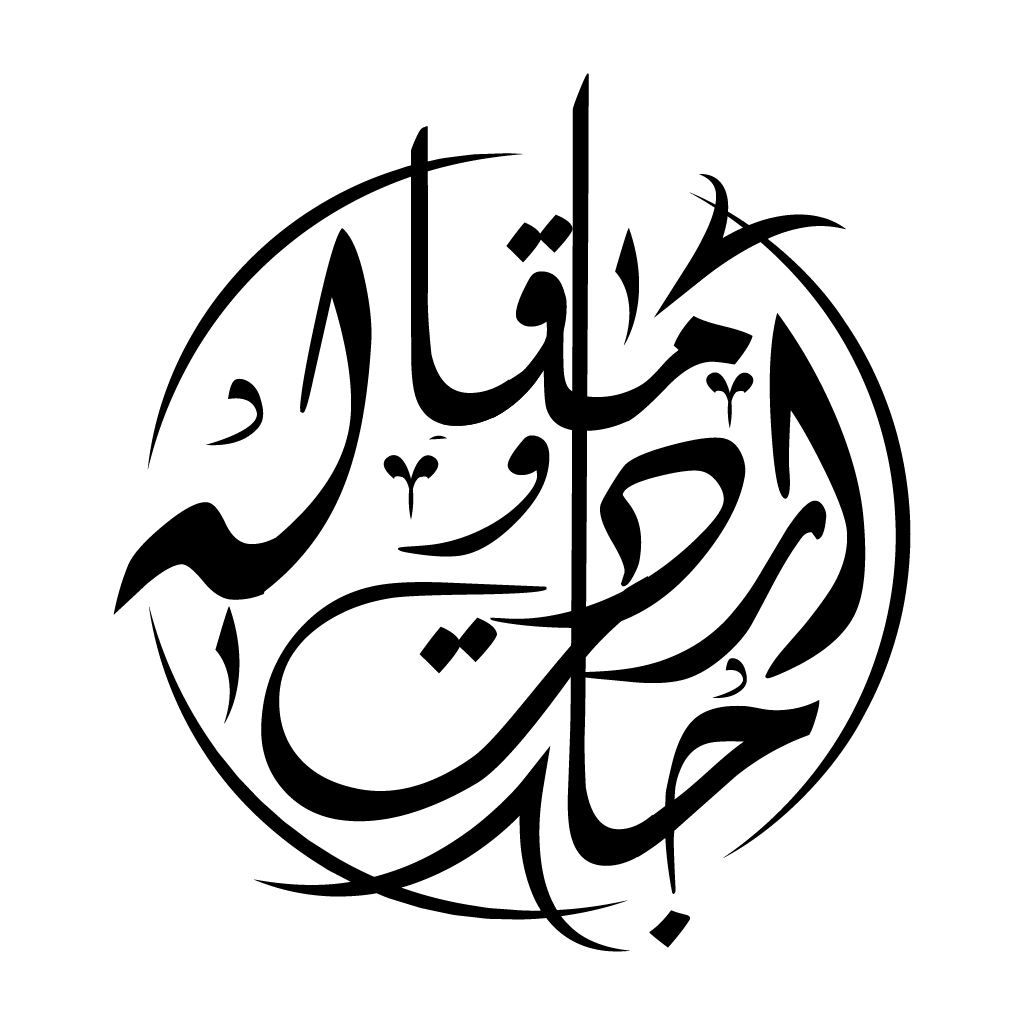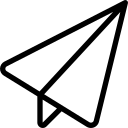اردو نظم کا تحقیقی جائزہ لیتے وقت ہمیں اردو شاعری کی ابتدائی جہات، اس کے ارتقائی مراحل، اصنافِ نظم کی تبدیلی، موضوعاتی تنوع، لسانی اور ہیئتی تجربات، اور سب سے بڑھ کر نظم کے ذریعے بدلتے ہوئے فکری اور تہذیبی شعور کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے۔ اردو نظم، جیسا کہ اس کا مفہوم ظاہر کرتا ہے، شعری اظہار کی وہ صنف ہے جو غزل کے روایتی، موضوعاتی اور ہئیتی سانچوں سے ہٹ کر ایک مربوط، مسلسل، منظم اور بعض اوقات بیانیہ انداز میں جذبات، خیالات یا کسی منظر کو پیش کرتی ہے۔ اگرچہ اردو شاعری میں غزل کو اوّلیت حاصل رہی ہے، تاہم نظم نے بتدریج اپنے انفرادی تشخص، فکری گہرائی، اور تہذیبی نمائندگی کے باعث ایسی اہمیت حاصل کی ہے کہ آج اسے اردو ادب کے اہم ترین فنی اور فکری مظاہر میں شمار کیا جاتا ہے۔
اردو نظم کی ابتدا دکن کے شعرا سے ملتی ہے، جنہوں نے قصیدے، مثنویاں اور مناجاتیں تخلیق کیں۔ محمد قلی قطب شاہ، نصرتی، اور وجہی نے نظم کی شکل میں قصیدہ، مرثیہ، اور مثنوی کو رائج کیا۔ اگرچہ ان کی زبان میں فارسی اثرات غالب تھے، مگر ان کے ہاں موضوعات کی وسعت، منظر نگاری اور بیانیہ انداز نظم کی ابتدائی بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ بعد ازاں شمالی ہند میں میر، سودا، اور میر حسن نے مثنویوں اور مراثی کے ذریعے اردو نظم کو ایک ادبی شناخت دی۔ میر حسن کی مثنوی “سحرالبیان” بیانیہ نظم نگاری کا ایک بلند مقام ہے جس میں رومانی داستان، کردار نگاری، اور منظر نگاری کو بڑی خوبی سے نظم کیا گیا۔
انیسویں صدی میں حالی، سرسید تحریک کے زیرِ اثر، اردو نظم کو ایک اصلاحی اور مقصدی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ حالی کی “مد و جزرِ اسلام”، “شکوۂ ہند”، اور سب سے بڑھ کر “مسدس حالی” اردو نظم کی تاریخ میں ایک انقلابی سنگِ میل ہے۔ انہوں نے شعر کو صرف اظہارِ جذبات سے نکال کر ایک اخلاقی، فکری اور تہذیبی مقصد سے وابستہ کیا۔ حالی کی نظم میں روایت سے انحراف بھی ہے اور اسلوب کی سادگی و برجستگی بھی۔ ان کے بعد اکبر الہ آبادی نے طنزیہ نظم کے ذریعے سماجی شعور، سیاسی آگہی، اور نوآبادیاتی نظام پر تنقید کو اردو شاعری کا حصہ بنایا۔ ان کی نظمیں محض ہنسی کا سامان نہیں بلکہ فکری بیداری اور تہذیبی مزاحمت کا نمونہ ہیں۔
اقبال کا ذکر کیے بغیر اردو نظم کی تاریخ نامکمل ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اردو نظم کو نہ صرف فکری اور فلسفیانہ بلندیوں تک پہنچایا بلکہ اسے ملتِ اسلامیہ کے خواب، خودی، فرد کی آزادی، قوم پرستی اور روحانی تجدید کا ذریعہ بنایا۔ ان کی نظمیں جیسے “شکوہ”، “جوابِ شکوہ”، “طلوع اسلام”، “خضرِ راہ”، “ذوق و شوق”، اور “مسافر” اردو نظم کی فکری گہرائی، ہیئتی تجربات، اور فنی رفعت کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ انہوں نے مثنوی، نظم، غزل سبھی اصناف میں جدید فکری عناصر سموئے لیکن ان کی نظم نگاری نے اردو شاعری کو عالمگیر فکر سے روشناس کرایا۔
اقبال کے بعد نظم میں کئی رجحانات اور تحریکیں پیدا ہوئیں، جن میں ترقی پسند تحریک سب سے نمایاں ہے۔ فیض احمد فیض، مجروح سلطانپوری، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جان نثار اختر، اور دیگر شعرا نے نظم کو انقلابی، اشتراکی، اور سامراج مخالف بیانیے کا ذریعہ بنایا۔ فیض کی نظمیں “مجھ سے پہلی سی محبت”، “دستِ صبا”، اور “نصاب” جیسے مجموعوں میں زبان و بیان کی لطافت، انقلابی جذبے کی شدت، اور انسانی دکھوں کی سچائی ملتی ہے۔ ترقی پسند نظم نے سماج، طبقاتی تفریق، آزادی، عورت، مزدور، کسان، اور جبر کے خلاف آواز کو شعری پیکر دیا۔
جدیدیت نے اردو نظم کو مزید پیچیدہ، علامتی، داخلی، اور تجریدی رنگ دیے۔ ن م راشد اور میراجی اس رجحان کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ راشد نے اپنی نظموں میں فلسفہ، وجودیت، مغربی اساطیر، اور علامت نگاری کا ایسا امتزاج پیش کیا جو اردو نظم کو ایک نئی فکری سطح پر لے گیا۔ ان کی نظم “حسن کوزہ گر”، “اندھا کباڑی”، اور “ابابیل اور کلرک” اردو نظم میں داخلی کرب، تنہائی، اور تہذیبی زوال کی عمدہ مثالیں ہیں۔ میراجی کی نظمیں، جو نفسیاتی پیچیدگی، جنسی لاشعور، اور علامتی گہرائی رکھتی ہیں، اردو نظم کی تعبیراتی امکانات کو وسیع کرتی ہیں۔
جدیدیت کے بعد ما بعد جدید نظم نگاروں نے نظم کی ساخت، زبان، اور مواد کو توڑ کر نئے اسلوب اپنائے۔ خرم سہیل، افتخار عارف، عباس تابش، اور کشور ناہید جیسے شعرا نے معاشرتی اور فردی الجھنوں کو ایسی زبان میں پیش کیا جو نہ صرف قاری کو چونکاتی ہے بلکہ اسے غور کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ اس دور کی نظم میں آزاد نظم، نثری نظم، اور پابند نظم سبھی رجحانات موجود ہیں لیکن سب کا ہدف فرد کی داخلی بےچینی، شناخت کا بحران، سیاسی زوال اور تہذیبی شکست و ریخت ہے۔
اردو نظم نے صرف مرد شعرا ہی نہیں بلکہ خواتین شعرا کی شمولیت سے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ پروین شاکر، فہمیدہ ریاض، زہرہ نگاہ، کشور ناہید، اور نسرین انجم بھٹی جیسی نظم نگار خواتین نے عورت کی شناخت، جذبات، محرومی، محبت، خود مختاری اور مزاحمت کو نہایت موثر انداز میں نظم کے قالب میں ڈھالا۔ ان کی نظموں نے اردو ادب میں تانیثی شعور کو تقویت دی اور عورت کو محض موضوع نہیں بلکہ تخلیق کار کے طور پر پیش کیا۔
لسانی سطح پر اردو نظم نے فارسی، عربی، اور دیسی زبانوں کے الفاظ، محاورات، اور تراکیب کو جذب کر کے ایک ایسی شعری زبان تخلیق کی ہے جو بیک وقت کلاسیکی اور جدید، مشرقی اور مغربی، داخلی اور خارجی عناصر کی حامل ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے بھی اردو نظم نے مثنوی، مسدس، رباعی، قطعہ، پابند نظم، آزاد نظم، اور نثری نظم جیسے تجربات کو بخوبی قبول کیا ہے اور ہر اسلوب میں فکر و جذبے کی کامیاب ترجمانی کی ہے۔
خلاصہ یہ کہ اردو نظم کا تحقیقی جائزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نظم محض ایک صنف نہیں بلکہ اردو ادب کی فکری، تہذیبی، جمالیاتی اور سیاسی روح کی نمائندہ ہے۔ اس نے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے رنگ، رخ اور رجحانات کو بدلا لیکن ہمیشہ انسان، اس کی زندگی، اس کے خواب، دکھ، اور مزاحمت کو اپنے مرکز میں رکھا۔ اردو نظم نے جہاں ایک طرف تہذیبوں کے تصادم، داخلی کشمکش، اور وجودی بحران کو سمیٹا، وہیں اس نے امید، حسن، سچ، مزاحمت اور انسان دوستی کا پیغام بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نظم کا مطالعہ محض ادبی جمالیات کا مطالعہ نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیبی شعور کا احاطہ بھی ہے، جو آج بھی اردو ادب کی روح اور مستقبل کا ضامن ہے۔