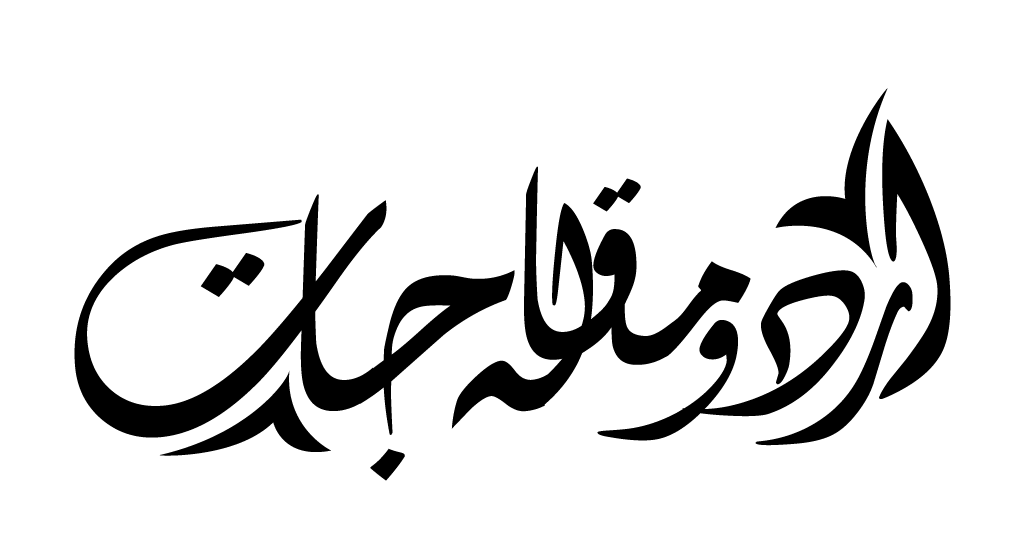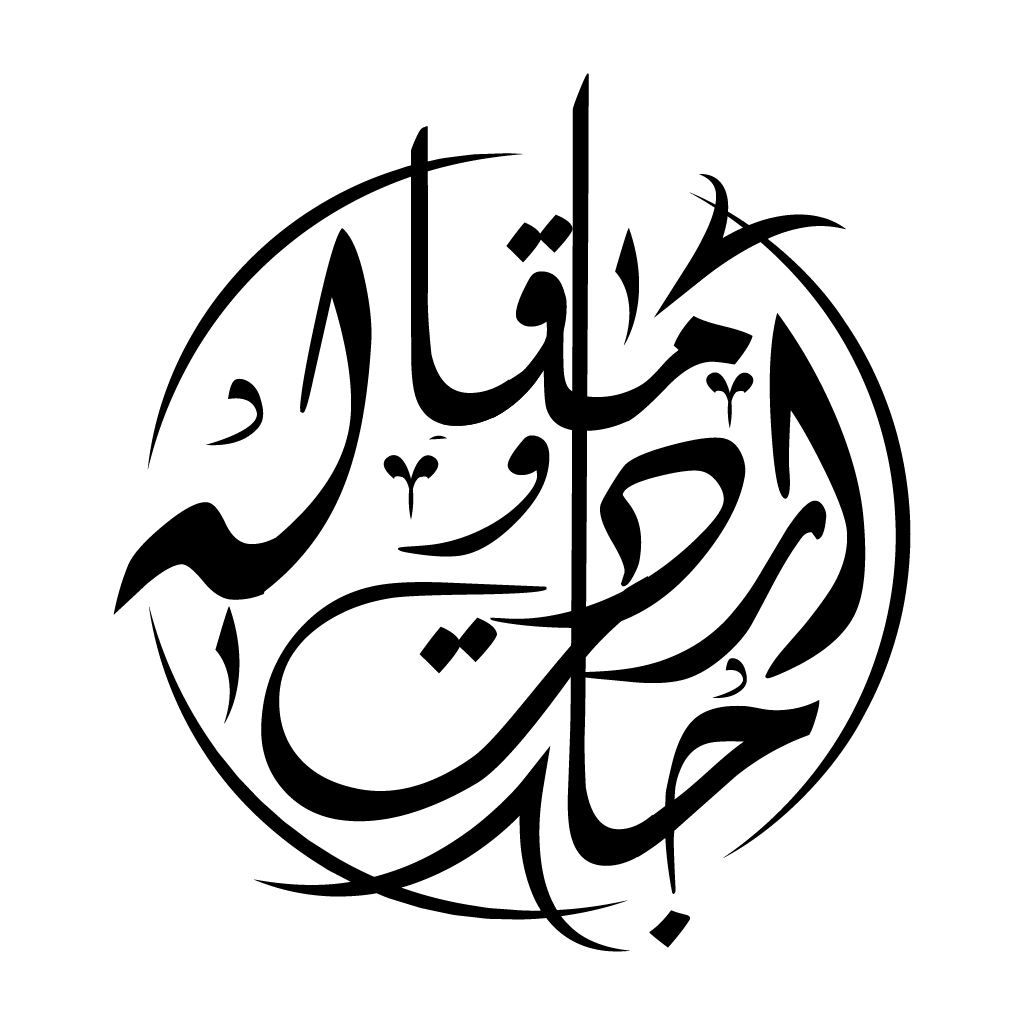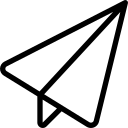سقوطِ ڈھاکا اردو ادب کی تاریخ کا وہ المیہ باب ہے جس نے صرف سیاسی اور عسکری تاریخ کو نہیں بدلا بلکہ اردو نثر، خصوصاً خودنوشت اور آپ بیتی کے اسلوب و مزاج کو بھی گہرے طور پر متاثر کیا۔ ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دیش کے قیام اور مشرقی پاکستان کے سقوط نے اہلِ قلم کے شعور میں ایک زلزلہ برپا کیا۔ مصنفین نے محسوس کیا کہ قومی تاریخ کی اس شکست کا تجزیہ محض سیاسی بیانیے سے ممکن نہیں، بلکہ اسے ذاتی تجربات، احساسات اور خود احتسابی کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سقوطِ ڈھاکا کے بعد اردو خودنوشتوں میں ایک نیا رجحان ابھرا — ایسا رجحان جسے تنقید کی اصطلاح میں نو تاریخی مطالعہ (New Historicism) کہا جاتا ہے۔ اس زاویۂ نظر کے تحت مصنف اپنے ذاتی تجربے کو وسیع تاریخی، ثقافتی اور سماجی سیاق میں رکھ کر پیش کرتا ہے۔ اس طرح تاریخ صرف بیرونی واقعات کا سلسلہ نہیں رہتی بلکہ انسان کے باطن، احساس اور فکر کا حصہ بن جاتی ہے۔
نو تاریخی تناظر میں سقوطِ ڈھاکا پر لکھی گئی اردو آپ بیتیوں میں ذاتی مشاہدہ اور اجتماعی تاریخ باہم مدغم نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ میں اگرچہ سقوطِ ڈھاکا سے متعلق تفصیلی بیان نہیں، لیکن پاکستانی بیوروکریسی، اقتدار کی سیاست، اور مرکز و مشرقی پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ شہاب نے اپنے بیوروکریٹک تجربے کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ریاستی مشینری میں ناانصافی، نسلی امتیاز، اور اقتدار کی غیر منصفانہ تقسیم نے وہ بیج بوئے جو آخرکار علیحدگی کی صورت میں پھوٹے۔ نو تاریخی مطالعے کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شہاب نامہ ایک ذاتی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی تاریخی خوداحتسابی ہے جو اقتدار کی زبان اور عوامی دکھ کے بیچ تعلق کو بے نقاب کرتی ہے۔
اسی طرح جنرل (ریٹائرڈ) کے۔ایم۔ عارف کی آپ بیتی ورکنگ وِد ضیاء میں سقوطِ ڈھاکا کے بعد کے پاکستان کی عسکری اور سیاسی صورتِ حال کا بیان ملتا ہے، مگر ماضی کی اس شکست کے اثرات ہر صفحے پر موجود ہیں۔ مصنف نے اگرچہ خود مشرقی پاکستان کے سقوط کے وقت براہِ راست محاذ پر نہیں تھے، لیکن وہ اس سانحے کو قومی وقار، عسکری نظم، اور سیاسی تدبر کی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نو تاریخی زاویے سے دیکھا جائے تو اس قسم کی آپ بیتیاں یہ بتاتی ہیں کہ سقوطِ ڈھاکا محض ایک جغرافیائی تقسیم نہیں بلکہ ایک فکری بحران بھی تھا — ایسا بحران جس نے قومی شناخت کے مفہوم کو ہی متزلزل کر دیا۔
اردو کی دیگر آپ بیتیوں میں جنہوں نے سقوطِ ڈھاکا کے اثرات کو اپنے بیانیے میں سمویا، ان میں محمودہ رضویہ کی میرے حصے کی روشنی، ممتاز مفتی کی علی پور کا ایلی اور الکھ نگری، اور قرة العین حیدر کی کارِ جہاں دراز ہے خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ممتاز مفتی کی تحریر میں سقوطِ ڈھاکا کو براہِ راست موضوع نہیں بنایا گیا، لیکن ان کی تحریروں میں جو روحانی اضطراب، فکری شکست، اور قومی خود احتسابی کا احساس ہے، وہ اسی المیے کی بازگشت محسوس ہوتا ہے۔ نو تاریخی مطالعے کے تحت مفتی کا یہ اعتراف کہ پاکستانی قوم نے اپنی داخلی کمزوریوں کو نظرانداز کیا، تاریخ کی اس نئی قرأت کو جنم دیتا ہے جس میں فرد کی نفسیات اور قوم کی اجتماعی لاشعور ایک دوسرے کے عکس بن جاتے ہیں۔
قرة العین حیدر کا بیانیہ ہمیشہ سے تاریخ اور ذات کے باہمی تعلق پر مبنی رہا ہے۔ ان کے ناولوں اور آپ بیتی نما تحریروں میں سقوطِ ڈھاکا کے پس منظر میں پاکستانی معاشرے کے فکری زوال اور تہذیبی بگاڑ کا نوحہ سنائی دیتا ہے۔ ان کے نزدیک مشرقی پاکستان کی علیحدگی محض ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ تہذیبی تفاوت اور سماجی ناہمواری کی علامت تھی۔ نو تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو قرة العین حیدر کی تحریریں یہ واضح کرتی ہیں کہ تاریخ کو محض ریاستی بیانیہ نہیں بلکہ ثقافتی اور نفسیاتی تجربہ سمجھنا چاہیے۔
اسی طرح حسن ناصر، صفدر میر، اور سلیم احمد جیسے اہلِ قلم کی تحریریں بھی اگرچہ مکمل خودنوشتیں نہیں تھیں، مگر ان کے خطوط، یادداشتوں اور تبصروں میں سقوطِ ڈھاکا کا فکری و جذباتی اثر نمایاں ہے۔ ان کے یہاں نو تاریخی رجحان اس صورت میں ابھرتا ہے کہ وہ تاریخ کو جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک متحرک عمل کے طور پر دیکھتے ہیں — ایسا عمل جو فرد کے شعور، سیاست کی ساخت، اور ادبی اظہار کو یکجا کرتا ہے۔
نو تاریخی مطالعے کے مطابق، ہر آپ بیتی اپنے زمانے کے طاقت کے ڈھانچوں، سماجی اقدار اور فکری رجحانات سے متاثر ہوتی ہے۔ سقوطِ ڈھاکا کے بعد لکھی جانے والی اردو خودنوشتیں دراصل اس بحران کی داخلی تعبیرات ہیں۔ ان میں مصنف نہ صرف واقعات بیان کرتا ہے بلکہ اُن واقعات کے اسباب و اثرات کو اپنی ذات کے تجربے سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اس طرح قاری کو محض تاریخ کا بیان نہیں بلکہ تاریخ کا زندہ احساس ملتا ہے۔
اگر سقوطِ ڈھاکا کے تناظر میں ان خودنوشتوں کا مجموعی تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان سب میں ایک مشترک رجحان پایا جاتا ہے: قومی المیے کو ذاتی دکھ کے ساتھ جوڑنا۔ یہ مصنفین اپنے عہد کے شاہد بھی ہیں اور شریکِ جرم بھی۔ ان کے لیے یہ آپ بیتیاں محض یادداشتیں نہیں بلکہ ایک طرح کا اعتراف نامہ ہیں — اعترافِ خطا، اعترافِ نادانی، اور اعترافِ شکست۔ یہی وہ نکتہ ہے جہاں نو تاریخی مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ادب تاریخ کا متبادل نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے۔
نتیجتاً کہا جا سکتا ہے کہ سقوطِ ڈھاکا کے تناظر میں لکھی گئی اردو آپ بیتیوں نے تاریخ اور ادب کے درمیان ایک نئی فکری فضا قائم کی۔ ان میں فرد کی آواز کے ذریعے قوم کی تاریخ بولتی ہے۔ مصنفین نے اپنے باطن میں جھانک کر اس سانحے کی جڑیں تلاش کیں، اور یوں اردو نثر میں ایک نیا باب رقم ہوا جس میں تاریخ محض ماضی نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ بن گئی۔ ان آپ بیتیوں کا نو تاریخی مطالعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سقوطِ ڈھاکا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ تھا جس میں پوری قوم نے اپنے چہرے کو پہلی بار حقیقت کی روشنی میں دیکھا — وہ روشنی جو شاید آج تک پوری طرح بجھی نہیں۔