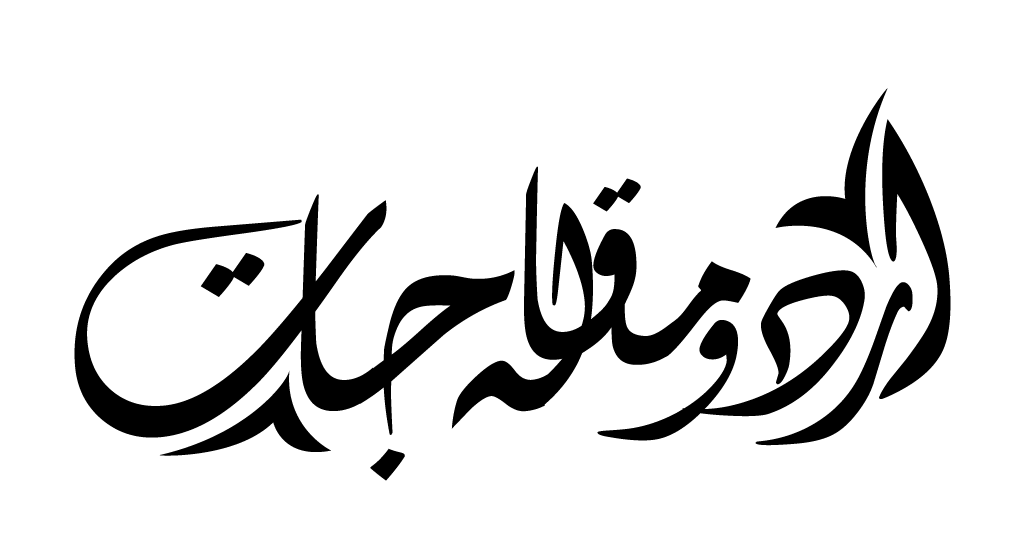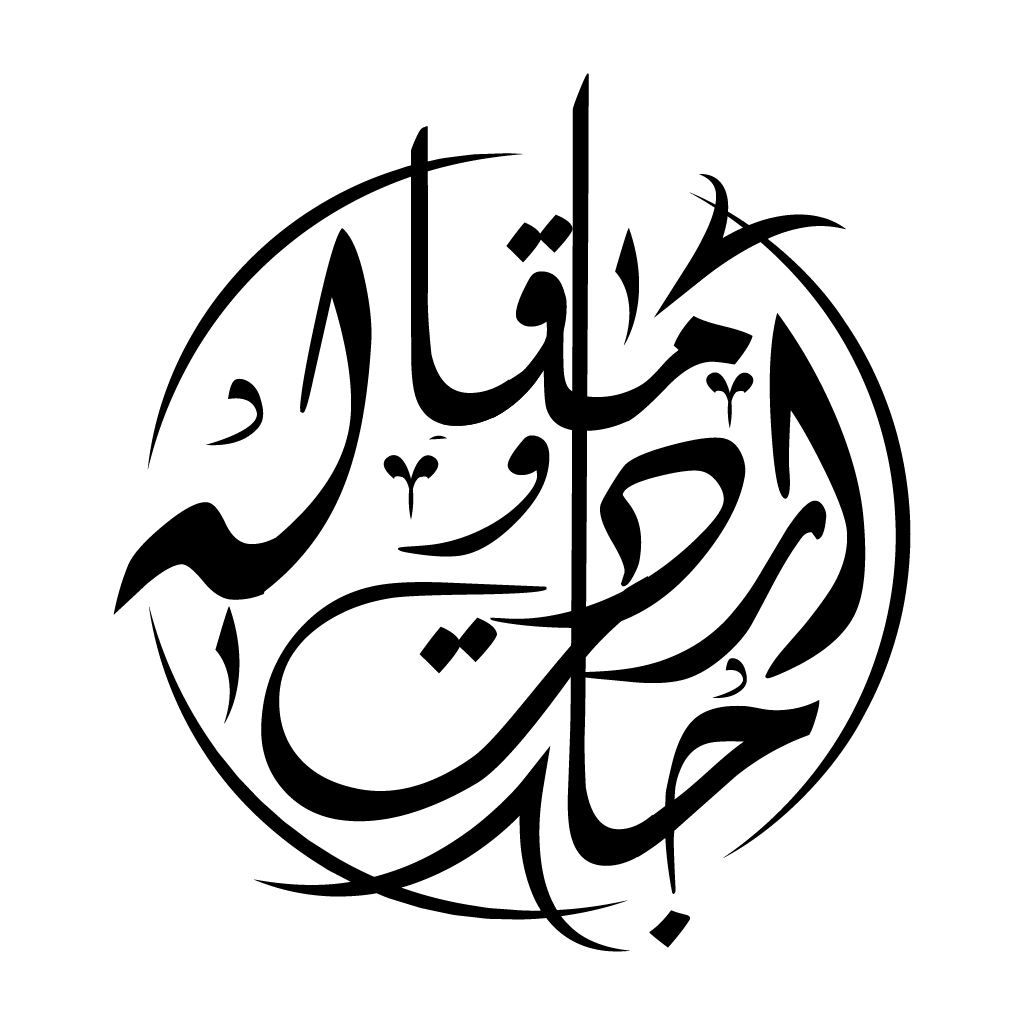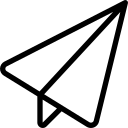اردو ڈرامہ اپنے ارتقائی سفر میں مختلف نظریات اور تکنیکی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ڈرامائی نظریہ دراصل ان اصولوں اور تصورات پر مشتمل ہوتا ہے جو ڈرامے کی ہیئت، ساخت، کرداروں، مکالموں اور منظرناموں کو تشکیل دیتے ہیں۔ اردو میں ڈرامہ نگاری کا آغاز فورٹ ولیم کالج کے ترجمہ شدہ ڈراموں سے ہوا لیکن باقاعدہ تخلیقی اظہار کی صورت اس کو دبستان دہلی اور بعدازاں لکھنؤ میں حاصل ہوئی۔ تاہم، کلاسیکی اردو ڈرامہ زیادہ تر اسٹیج کی تکنیکی ضروریات سے آزاد صرف مطالعے کے لیے لکھا جاتا رہا۔ اردو ڈرامے کی بنیاد غالباً فارسی اور یورپی اثرات پر مبنی تھی، لیکن جلد ہی اس نے ہندی اور ہندوستانی لوک روایت سے بھی اثرات قبول کیے۔
انیسویں صدی کے اواخر میں آغا حشر کاشمیری نے ڈرامے کو اسٹیج کے لیے مخصوص پیرایہ اظہار عطا کیا۔ انہوں نے شیکسپیئر کے ڈراموں سے متاثر ہو کر اردو ڈرامے کو جذباتی شدت، مکالماتی سحر، اور منظر نگاری کی جاذبیت دی۔ آغا حشر کے ڈرامے کلاسیکی ہندوستانی اسٹیج پر پیش کیے جانے کے لیے موزوں تھے، جن میں روشنی، منظرنامہ، اور کرداروں کی آواز و اداکاری اہم حیثیت رکھتے تھے۔ اس عہد میں ڈرامے کا بنیادی مقصد تفریح اور معاشرتی اصلاح تھا۔ موضوعات عموماً عشقیہ، مذہبی، یا سماجی نوعیت کے ہوتے اور تکنیکی طور پر ان میں منظر تبدیلی، مکالمہ نگاری، اور اسٹیج حرکات کو خصوصی اہمیت دی جاتی۔
انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے آغاز میں اردو ڈرامہ تحریکات اور نظریات سے متاثر ہونے لگا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ڈرامے میں سماجی ناہمواری، طبقاتی کشمکش، اور ظلم کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ ان ڈراموں میں تکنیکی سادگی کے ساتھ ساتھ نظریاتی گہرائی بھی پیدا ہوئی۔ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو اور بیدی جیسے افسانہ نگاروں نے بھی ریڈیو اور تھیٹر کے لیے ڈرامے لکھے، جن میں فنی مہارت اور نظریاتی وابستگی کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔
ریڈیو کی آمد نے اردو ڈرامہ کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ اب ڈرامے کو اسٹیج کی بجائے آواز کی دنیا میں منتقل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مکالمے کی اہمیت بڑھ گئی اور منظر نگاری کی بجائے آہنگ، لب و لہجہ، اور صوتی تاثرات پر زور دیا جانے لگا۔ اس دوران نورالحسن، احتشام الدین، اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جیسے مصنفین نے ریڈیو ڈرامے کو بام عروج تک پہنچایا۔ اشفاق احمد کے “تلقین شاہ” اور بانو قدسیہ کے “میری ذات ذرۂ بے نشان” جیسے ڈراموں نے سامعین کے دلوں کو چھوا۔
اسی عرصے میں ٹیلی ویژن کے ذریعے اردو ڈرامے کی ایک نئی جہت سامنے آئی۔ یہ عہد فنی لحاظ سے اردو ڈرامے کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ حسینہ معین، امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، منو بھائی، اشفاق احمد اور بانو قدسیہ نے جو ٹی وی ڈرامے تحریر کیے، ان میں معاشرتی حقیقت نگاری، کرداروں کی نفسیاتی تشکیل، اور مکالمے کی برجستگی قابل ذکر ہیں۔ ٹی وی ڈرامے نے “تکنیکی وحدت” کا خیال پیش کیا، جس کے تحت ہر منظر کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ مکمل وحدت کا حامل ہو۔ کیمرہ زاویہ، روشنی، پس منظر، لباس، اداکاری اور مکالمے سب اس نظریے کے تحت مربوط دکھائی دیتے تھے۔
ڈرامائی تکنیک میں جو عناصر نمایاں حیثیت رکھتے ہیں ان میں “منظر ترتیب”، “کردار سازی”، “مکالمہ نگاری”، “تصادم” اور “حل” شامل ہیں۔ ان عناصر کو اگر کسی اردو ڈرامہ نگار نے بحسن و خوبی استعمال کیا ہے تو وہ امجد اسلام امجد ہیں جن کے ڈرامے “وارث”، “دشت” اور “سمندر” آج بھی تکنیکی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں کرداروں کی تہہ داری، داخلی کشمکش، اور منظرناموں کی فنی چابک دستی نمایاں ہے۔ اسی طرح حسینہ معین نے نسوانی کرداروں کو نئی معنویت عطا کی۔ ان کے ڈراموں میں گفتگو کی نرمی، جذبات کی شفافیت، اور تکنیکی ساخت کا توازن قائم دکھائی دیتا ہے۔
نئے اردو ڈرامے میں بھی تکنیکی تجربات کیے گئے ہیں۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے اثرات نے اردو ڈرامے میں حقیقت کو ٹکڑوں میں پیش کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ نون میم راشد کے افکار سے متاثر مصنفین نے غیر خطی بیانیہ، علامتی انداز، اور تجریدی عناصر کو ڈرامے میں داخل کیا۔ ان عناصر کے باعث ناظر کی شمولیت بڑھ گئی، اور اسے کہانی کو جوڑنے اور معانی اخذ کرنے میں خود حصہ لینا پڑا۔ پوسٹ ماڈرن اسلوب میں وقت و مکان کے تعین کو توڑ کر ایک نئی تجرباتی فضا قائم کی گئی، جیسے کہ سراج منیر کے بعض ڈراموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔
تکنیکی پہلو سے دیکھا جائے تو جدید اردو ڈرامہ نہ صرف مقامی روایات بلکہ عالمی تکنیکی امکانات سے بھی اثر پذیر ہے۔ مثلاً ناظر کی سمت میں براہ راست مکالمہ (breaking the fourth wall)، روشنی اور سائے کا علامتی استعمال، آوازوں کی معنویت، کیمرہ حرکت اور تدوین (editing) جیسے پہلو ڈرامے کو صرف کہانی سنانے کی بجائے ایک بصری اور صوتی تجربہ بنا دیتے ہیں۔
مگر حالیہ برسوں میں اردو ڈرامہ تجارتی دباؤ کا شکار ہو کر کئی تکنیکی اقدار سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ لمبی قسطوں میں کھینچی ہوئی کہانی، موضوعات کی سطحیت، کرداروں کی تکرار، اور مکالمہ نگاری کی سطحیت نے ڈرامے کی سنجیدہ فنی حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ تاہم اب بھی بعض تخلیق کار جیسے خلیل الرحمان قمر یا عمیرہ احمد ایسے ڈرامے لکھتے ہیں جن میں تکنیکی سوجھ بوجھ اور فکری گہرائی موجود ہوتی ہے، اگرچہ ان پر کئی تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں۔
اردو ڈرامہ، چاہے وہ اسٹیج، ریڈیو، یا ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو، اپنی فنی ساخت اور ڈرامائی نظریات کے تناظر میں ایک اہم ادبی صنف ہے۔ اس میں جہاں ادبی ذوق کی آبیاری ہوئی ہے، وہیں سماجی شعور، سیاسی بیداری، اور تہذیبی اقدار کی جھلک بھی ملتی ہے۔ اردو ڈرامہ نہ صرف ہمارے ثقافتی تجربے کا آئینہ دار ہے بلکہ ایک فنی تجربہ بھی ہے جس میں کہانی، منظر، مکالمہ اور کردار سب مل کر زندگی کے رنگ بکھیرتے ہیں۔