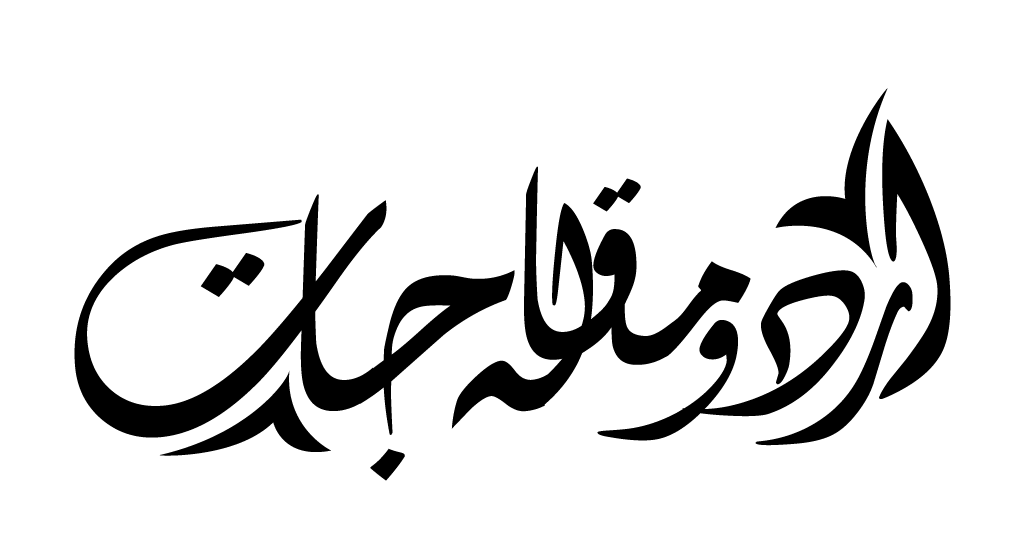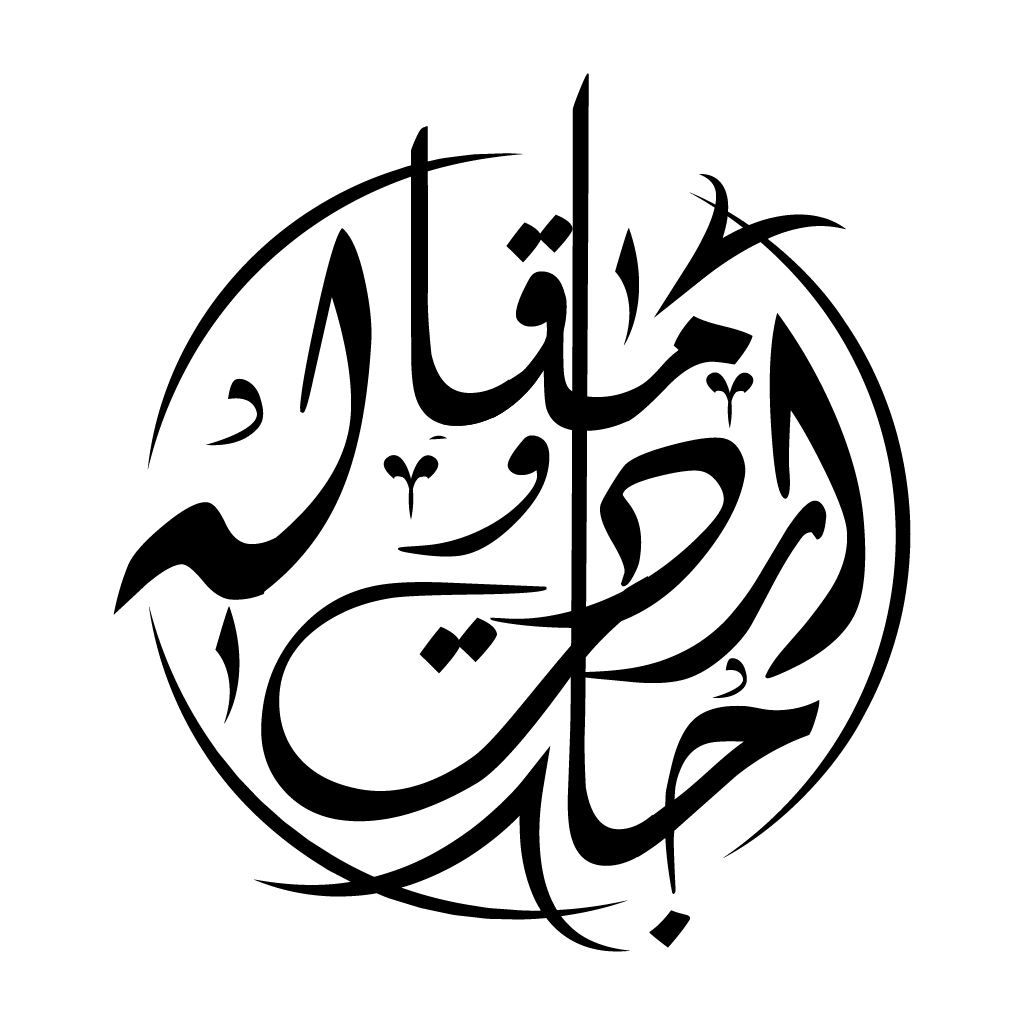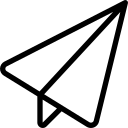غلام ہمدانی مصحفی اٹھارہویں صدی کے اردو شاعری کے ایک اہم اور مرکزی شاعر تھے، جنہیں نہ صرف اپنے عہد میں بلکہ بعد ازاں اردو غزل کے کلاسیکی نقوش کی تشکیل میں بھی خاص مقام حاصل ہوا۔ وہ 1751ء میں اٹاوہ (یو پی) میں پیدا ہوئے اور 1824ء میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ مصحفی ایک کثیر اللسان اور کہنہ مشق شاعر تھے جنہوں نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شعر کہے، لیکن ان کی شہرت اردو شاعری خصوصاً اردو غزل کے باعث ہوئی۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی، فیض آباد اور بالآخر لکھنؤ میں گزرا، جہاں انہوں نے درباری سرپرستی کے ساتھ ساتھ شاعری، تدوین، انتخاب، اور تنقیدی حوالوں سے کئی علمی کام کیے۔ ان کی شخصیت نہایت رنگا رنگ، صاف گو اور خوددار واقع ہوئی تھی، اور ان کی شاعری میں جو فطری روانی، داخلیت، اور کلاسیکی مزاج ملتا ہے، وہ انہیں اپنے عہد کے ممتاز شعرا میں ممتاز کرتا ہے۔
مصحفی کی شاعری کا بنیادی حوالہ غزل ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں محبوب کے حسن، فراق، بےوفائی، اور جذباتی کشمکش کے ساتھ ساتھ خود اپنی شخصیت کی کئی تہیں بھی واشگاف انداز میں پیش کیں۔ ان کی غزلوں میں ایک طرح کی نفسیاتی سچائی، داخلیت، اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ مرزا رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد جیسے شعرا کے ہم عصر اور جزوی طور پر شاگرد بھی سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اسلوب میں جو انفرادیت پیدا کی، وہ انہیں ایک خودمختار اور جداگانہ آواز عطا کرتی ہے۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو:
کیا بتاؤں کہ کیا مزا ہے وصال میں
جان نکلے، تو دل نکل جائے حال میں
یہ شعر جہاں عاشقانہ جذبات کی شدت کی عکاسی کرتا ہے، وہیں مصحفی کے سادہ مگر پُراثر اسلوب کی بہترین مثال بھی ہے۔
غلام ہمدانی مصحفی نے اردو غزل کو حسنِ بیان، سادگی، نفاست، اور فکری تنوع دیا۔ ان کے ہاں نہ تو میر کی طرح درد و الم کی شدت ہے، اور نہ سودا کی طرح فخریہ خودی، بلکہ ان کی غزل میں ایک نرم مزاجی، خود احتسابی، اور زندگی کے عام تجربات کا بیان ہے۔ ان کے اشعار میں شخصیت کا عکس نظر آتا ہے، اور وہ شاعری کو محض مبالغہ آرائی یا صنم پرستی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس میں انسانی کمزوریوں، جذباتی اتار چڑھاؤ، اور خود احتسابی کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے۔
ایک محقق کی حیثیت سے مصحفی کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم ان کے تیار کردہ تذکروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا مشہور تذکرہ تذکرہ شعرائے ہند اردو شعرا کے حالات و کلام کا ایک اہم اور قدیم ماخذ ہے، جس میں انہوں نے متعدد شعرا کے حالات، نمونہ کلام، اور تنقیدی آرا درج کی ہیں۔ اگرچہ ان کے بعض بیانات میں شخصی عناد یا ذاتی تاثرات کا شائبہ نظر آتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے تذکرے کو اردو ادب کی تاریخ میں بنیادی حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تذکرے میں مصحفی نے اپنے ہم عصر شعرا کا جس انداز میں تنقیدی تجزیہ کیا ہے، وہ اردو تنقید کی ابتدائی شکل کے طور پر قابلِ قدر ہے۔
مصحفی کی ایک اور اہم خصوصیت ان کی تدوینی اور انتخابی خدمات ہیں۔ انہوں نے مختلف شعرا کے دیوانوں کی تدوین اور ترتیب میں مدد دی اور کئی ایسے متون کو محفوظ کیا جو وقت کے ساتھ ضائع ہو سکتے تھے۔ ان کی تدوینی کاوشیں اگرچہ آج کی سائنسی تحقیق کے معیار پر نہیں اترتیں، مگر ان کی زبان فہمی، عروضی بصیرت، اور شعری ذوق نے انہیں اس میدان میں ممتاز رکھا۔ ان کے ذاتی دیوانوں کی تعداد متعدد ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پچاس ہزار سے زائد اشعار کہے، جن میں سے ایک بڑا حصہ محفوظ ہے۔
مصحفی کی شاعری میں جو اسلوبی تنوع ملتا ہے، وہ ان کے تجربات اور مشاہدات کی وسعت کا مظہر ہے۔ ان کے یہاں ہجر و وصال، عاشقانہ بیقراری، مذہبی خیالات، تہذیبی تنقید، اور انسانی رویوں کا مشاہدہ بھرپور انداز میں موجود ہے۔ ان کا انداز نہایت رواں، سادہ، فصیح، اور گہری معنویت کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر تکرار یا سادگی حد سے بڑھ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر ان کی غزلیں زبان کی مٹھاس، فکر کی ندرت، اور جذبے کی شدت سے لبریز ہوتی ہیں۔
تنقیدی لحاظ سے دیکھا جائے تو مصحفی کی شاعری کو میر اور سودا کے درمیانی مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں میر کی طرح سوز نہیں، لیکن ایک خاموش درد ضرور ہے، اور سودا کی طرح طمطراق نہیں، مگر ایک اعترافی صداقت ضرور ہے۔ ان کا شعری لہجہ اعتدال پسند، خود احتسابی پر مبنی، اور بعض اوقات ظریفانہ طنز سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی اسلوب بعد کے کئی شعرا مثلاً ناسخ، آتش، جرات، اور یہاں تک کہ غالب تک پر اثر انداز ہوا۔
آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ غلام ہمدانی مصحفی اردو ادب کے ایک ایسے ہمہ جہت شاعر تھے جنہوں نے اردو غزل کو نہ صرف داخلی تجربے، زبان کی چاشنی، اور تہذیبی شعور سے مالا مال کیا بلکہ اردو تذکرہ نگاری اور تنقید میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری میں جو فکری توازن، جذباتی سچائی، اور زبان کا حسن ہے، وہ آج بھی انہیں اردو کلاسیکی شعرا میں ممتاز کرتا ہے۔ ان کے بغیر اردو غزل کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اور ان کا کلام اردو ادب کے تحقیقی و تنقیدی مطالعات کے لیے ہمیشہ ایک وقیع ماخذ رہے گا۔