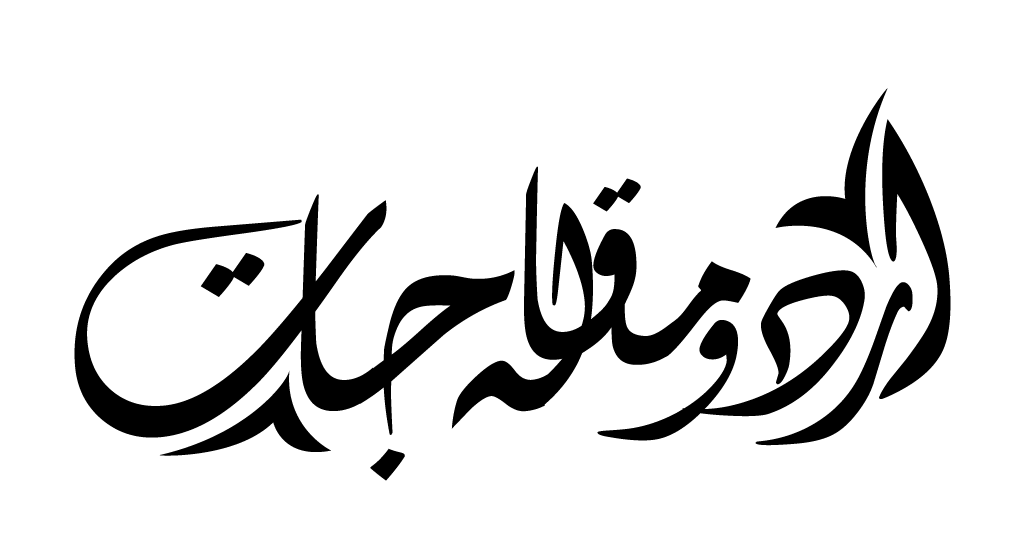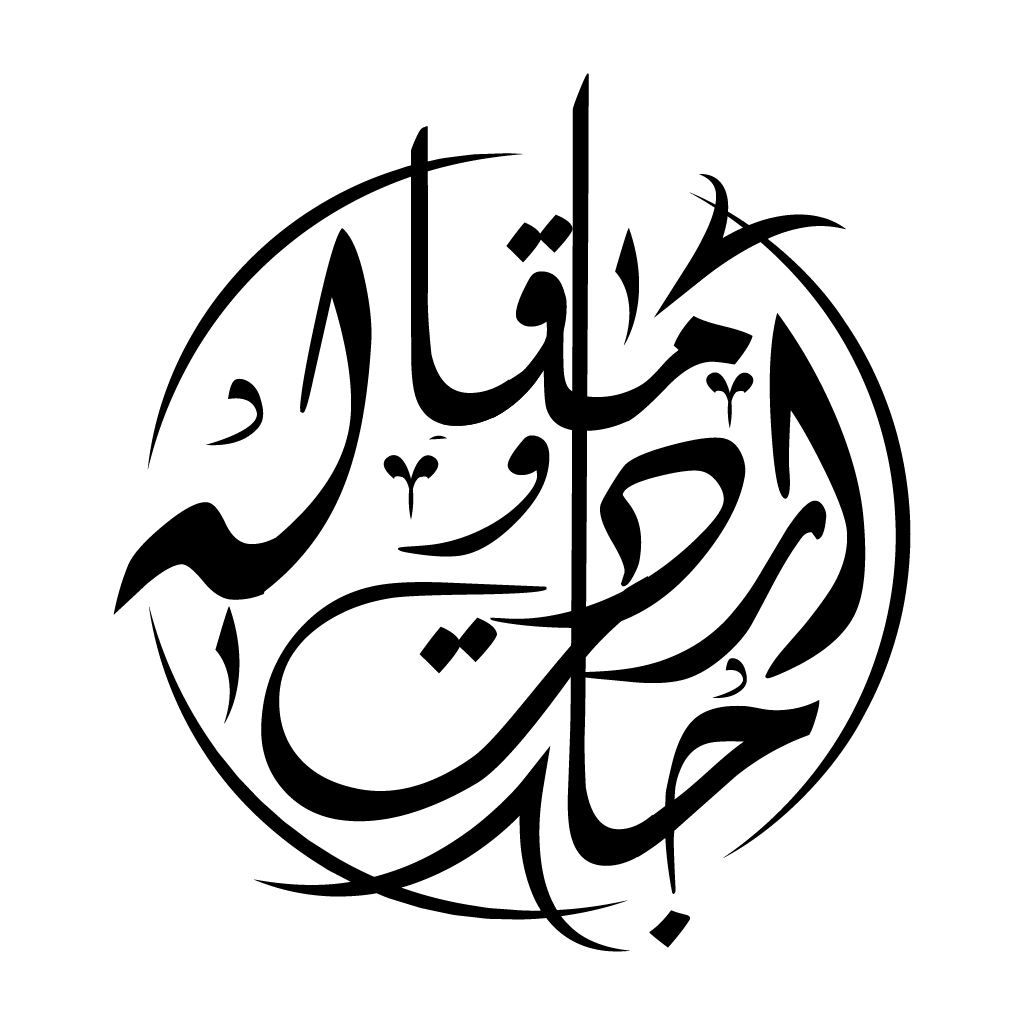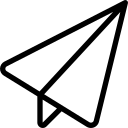اقبال کے تصورات اصل میں اسلامی نظریات سے ماخوذ ہیں۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر نہ صرف راہ نمائی کرتاہے بلکہ عملی مثالیں بھی پیش کرتاہے ۔ اقبال کے افکار و نظریات آفاقی ہیں۔ آپ جس پس منظر سے اقبال کی تفہیم کرناچاہیں، افکار اقبال اسی سانچے میں بصیرت کے دروازے کھولتے نظرآتے ہیں۔ اقبال نے اسلام کے سیاسی و معاشی نظام کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے ملت کی بقااور استحکام کے لیے قلم کااستعمال کیا۔ خاص طور پر جب اقبال پر یہ حقیقت اشکار ہوئی کہ امت مسلمہ کے سیاسی زوال کی پہلی وجہ طاقت سے محرومی ہے ۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں دو ٹوک بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں:
تقدیر کے قاضی کایہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرمِ ضعیفی کی سزامرگِ مفاجات (1)
ایک مضبوط اور مؤثر سیاسی نظام کی بقاکے لیے طاقت ایک لازمی عنصر ہے ، اور اسلامی نقطہ نظر میں اسے ناپسندیدہ نہیں سمجھاجاتا۔ موجودہ دور کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو امتِ مسلمہ کامستقبل غیر یقینی دکھائی دیتاہے ۔ علامہ اقبال نے اپنے انگریزی مضمون “مسلم سیاست” میں مسلمانوں کے زوال کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔ ان کے مسلسل غوروفکر سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ امت مسلمہ اپنی عملی قوت کھو چکی ہے اور اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کے عزم و عمل کی روایات کو نظرانداز کر چکی ہے ۔
علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے مسائل کاگہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اس مقصد کی طرف توجہ مرکوز کی کہ اپنی ملت میں کھوئی ہوئی عظمت اور طاقت کاشعور پیداکریں اور اس میں نئی روح پھونکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک فلسفہ وضع کیاجس کامحور ملت کی تجدیدِ حیات تھا۔ خودی، مومن، ملت، حاکمیت، اور اجتہاد جیسے فلسفیانہ تصورات، جن میں سیاسی پہلو بھی شامل تھے ، اقبال کے افکار کاحصہ بنے ۔ انہوں نے ان تصورات کو الفاظ کاجامہ اس لیے پہنایاتاکہ ان کے ذریعے اپنی قوم کو جرات، طاقت، عزم، اور حوصلے کاپیغام دے سکیں۔
موجودہ دور میں امت مسلمہ ان تمام عناصر سے محروم ہے جو اس کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ اقبال کے افکار آج کے پیچیدہ مسائل میں گھرے ہوئے معاشروں کے لیے شفاکاذریعہ بن سکتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک طاقت اور قوت کے حصول کاتصور بے قابو نہیں ہے بلکہ محدود ہے ۔ مسلم معاشرے میں حاکمیت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے ، اور ملت اسلامیہ کو اللہ کی جماعت قرار دیاگیاہے ۔ تمام عالم وجود میں اسلام کاواحد حاکم اعلیٰ ہے ، جو نہ صرف قوانین وضع کرتاہے بلکہ نظام حیات پر مکمل اختیار بھی رکھتاہے ۔ وہی ریاست کی بقااور استحکام کی اصل بنیاد ہے ۔ ڈاکٹر پروین شوکت قران کے اس تصور کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کامالک ہے ۔ تم جہاں بھی اپنی سوچ کو مڑ کر دیکھو گے ، وہاں اللہ کی قدرت کے آثار نظر ائیں گے ۔ اللہ پوری کائنات کو اپنی قدرت کے دائرے میں گھیرے ہوئے ہے اور ہر ذرے کاعلم رکھتاہے ۔(2)
اقبال کانظریہ حاکمیت توحید کے تصور سے گہراتعلق رکھتاہے اور اس سے جدانہیں کیاجاسکتا۔ ان کے نظریے سے یہ واضح ہوتاہے کہ اللہ کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ حاکمیت اور توحید دراصل ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، اور ملت اسلامیہ کی سیاست کی بنیاد اسی توحید پر قائم ہے ۔ ڈاکٹر پروین شوکت اس حوالے سے لکھتی ہیں:
اقبال اس امرسے باخبرتھے کہ حاکمیت اورتوحید کے ربط کی بناپرغیرمسلم ناقد ین کویہ کہنے کاموقع ملاکہ اسلام خالص مذہبی حکومت کی تلقین کرتاہے ۔ وہ اس کی پرزور تردید کرتے ہیں کہ جلد بازی میں یہ فیصلہ کرلینااس امرکی د لیل ہے کہ نقاد صحیح اسلامی اصولوں سے ناواقف ہیں۔(3)
اللہ کی حاکمیت کانظریہ انسان کے نظامِ زندگی سے دین اور سیاست کی علیحدگی کے تمام امکانات کو ختم کر دیتاہے ۔ موجودہ دور میں مغربی سیاسی فکر کاسب سے اہم کارنامہ دین اور سیاست کے درمیان تفریق پیداکرناہے ۔ اقبال نے اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں مذہب اور سیاست کے باہمی تعلق کو بڑی اہمیت دی۔ ان کے خیال میں مذہب اسلام افراد کی زندگی میں مکمل راہنمائی کرتاہے ۔ یہ نہ صرف انفرادی سطح بلکہ اجتماعی سطح پر بھی راہنمائی کرتاہے ۔ اقبال نے اسلامی تعلیمات کو سیاسی و سماجی ڈھانچے میں لاگو کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی معاشرتی و سیاسی نظام میں اصول و ضوابط کو عالمی سطح پر نافذ کیاجاناچاہیے ۔ اقبال کے نزدیک وہ سیاست جو مذہبی اصولوں اور پابندیوں سے آزاد ہو، ایک شیطانی نظام ہے ، اور ایسی سیاست بے لگام ہے ۔ اقبال ضربِ کلیم میں لکھتے ہیں۔
میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین
کنیزِ اہرمن و دوں نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترکِ کلیساسے حاکمی آزاد
فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر
متاعِ غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی
تو ہیں ہراول لشکر کلیساکے سفیر(4)
اقبال عالم اسلام میں اس تصور کی مقبولیت سے نالاں تھے اور چاہتے تھے کہ اہل مغرب کی اندھی تقلید سے بچاجائے ۔ اقبال نے مغربی جمہوریت، سرمایہ داری، اور سوشلسٹ نظام پر گہری تنقید کی۔ ان کاخیال تھاکہ مغربی نظاموں میں انسانیت کی فلاح کی بجائے مفاد پرستی اور استحصال کارجحان ہے ۔ انہوں نے مغربی جمہوریت کو “غلامی” کے ایک نئے روپ کے طور پر دیکھا، جہاں عوام کے جذبات کو چمکایاجاتاہے لیکن حقیقی طاقت ہمیشہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے ۔ انھوں نے مغربی تہذیب اور ثقافت کو گہری نظر سے دیکھااور ان پر تبصرہ کیا۔ ان کی تحریروں اور شاعری میں مغرب کی تقلید پر تنقید کی گئی ہے ، اور اس کی جگہ اسلامی ثقافت و تہذیب کو اپنانے کی اہمیت پر زور دیاگیاہے ۔ اج کے دور میں اقوام اس تقلید کاخمیازہ بھگت رہی ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک صرف نام کے اسلامی رہ گئے ہیں۔ اقبال کی فکر ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتی ہے ۔ موجودہ دور میں اسلامی نظام کے لیے اس ذہنی رویے سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں ہو سکتاکہ دین اور سیاست کو الگ کر دیاجائے۔ اقبال کو مکمل یقین تھاکہ مذہبی حدود و قیود سے ازاد ہو کر جو بھی سیاسی نظام اپنایاجائے گا، وہ اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اقبال لکھتے ہیں:
دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت
ہے ایسی تجارت میں مسلمان کاخسارا(5)
حاکمیت کے سیاسی پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد، اقبال نے امت مسلمہ کے لیے اجتہاد کے تصور کو اجاگر کیا۔ اقبال ان چند بصیرت رکھنے والوں میں شامل تھے جو مذہب اور سیاست دونوں میں اجتہاد کی حمایت کرتے تھے ۔ ان کامانناتھاکہ مسلمانوں کے زوال کے اہم اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فکرو عمل میں اجتہاد کی روح سے محروم ہو چکے ہیں۔ اقبال اکثر اپنے مکاتیب میں تمام مسلم اقوام کی اخلاقی، روحانی اور سیاسی پستی پر اظہار خیال کرتے تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ برصغیر کے علما دین اسلام کی امامت کافریضہ انجام دیں۔ زمانے کے حالات اور واقعات نے اقبال کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیاکہ اجتہاد ہی وہ ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو فکری جمود اور تعطل سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتاہے ۔
اقبال اسلامی سنہری دور سے متاثر تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر زور دیاکہ وہ تحقیق اور فکری جستجو کے اس جذبے کو دوبارہ زندہ کریں جو اسلام کے ابتدائی دور کاخاصاتھا۔ ان کاخیال تھاکہ اجتہاد کو اپنانے سے مسلمان اسلامی اصولوں کو جدیدیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں اور انفرادیت، عقلیت اور سماجی انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اجتہاد ایک متحرک اور ارتقائی عمل ہے ۔ اقبال کے چھٹے خطبے کاحوالہ دیتے ہوئے پروفیسر عثمان لکھتے ہیں:
اسلام کے مطابق تمام زندگی کی روحانی اصل ابدی ہے جو اپنی اظہار میں تبدیلی کرتی ہے ، لہٰذاجو معاشرہ حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جمود کے تمام امکانات کو ختم کر دے ۔ اس کے پاس اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے ابدی اصول ہوں کیونکہ مسلسل تبدیلی کی اس دنیامیں ابدی قدروں سے وابستگی ہمیں استقامت بخشتی ہے ۔۔۔ پچھلے پانچ سو سالوں میں اسلام پر اس وجہ سے جمود طاری ہے کہ مسلمانوں نے تبدیلی کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔(6)
اقبال کے نزدیک اجتہاد اور مسلم دنیا کی اصلاح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اجتہاد کو ایک ایسا ذریعہ سمجھتے ہیں جس کے ذریعے مسلمان نہ صرف موجودہ دور کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں بلکہ باہمی اتحاد اور سیاسی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اقبال اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ مغربی تسلط کے باعث مسلمانوں میں ایک غلامانہ ذہنیت پیدا ہو چکی ہے، جو انہیں اس طرف لے جا سکتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے مغربی نظریات کو اجتہاد کے نام پر اسلام کا حصہ بنا لیں۔ اس زمانے میں مشرقِ وسطیٰ اور ایشیا کی کئی قومیں مغربی اثرات کا شکار ہو رہی تھیں، جس پر اقبال کو تشویش تھی۔ اس کو علامہ اقبال ضرب کلیم میں اس طرح بیان کرتے ہیں:
کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیل
ہندی بھی فرنگی کامقلد عجمی بھی
مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد
کھو بیٹھے ہیں مشرق کاسرور ازلی بھی (7)
مغرب پسندی ایک خطرناک تقلید ہے اور اسے اجتہاد کہنااس نظریے کی اصل حقیقت سے نااشنائی کی علامت ہے ۔ اقبال نے مسلمانوں کو مغرب کی تقلید کی بجائے اپنی اصل شناخت یعنی اسلامی تعلیمات اور ثقافت کو اپنانے کاسبق دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی “خودی” کو پہچاننے کی دعوت دی، تاکہ وہ نہ صرف اپنی دنیامیں کامیاب ہوں بلکہ ایک متوازن اور اخلاقی معاشرت کی بنیاد بھی رکھیں۔ اقبال نے اسلامی معاشرت، سیاست، اور معاشیات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انھوں نے مغرب کی تقلید کو مسلمانوں کی تنزلی اور کمزوری کاسبب سمجھااور اس کے بجائے اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کاپیغام یہ تھاکہ مسلم دنیاکو مغربی نظاموں کی اندھی تقلید کی بجائے اپنی اصل تعلیمات اور تہذیب کو اپنے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظام میں نافذ کرناچاہیے ۔ “اجتہاد” نامی نظم میں اقبال لکھتے ہیں:
حلقہ شوق میں وہ جرات اندیشہ کہاں
آہ ! محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق !
خود بد لتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق ! (8)
اقبال کے افکار میں سب سے اہم نظریہ خودی ہے اور سیاسی، سماجی، اور معاشرتی لحاظ سے بھی یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے ۔ اقبال کی سیاسی تفہیم ان کے فلسفہ خودی سے جڑی ہوئی ہے ۔ عام خیال یہ ہے کہ اقبال کانظریہ خودی مسلمانوں کے معاشرتی زوال اور انحطاط کے ردعمل کے طور پر پروان چڑھاتھا، جو ان کے ذہن پر غالب تھا۔ چونکہ عام طور پر خودی کو غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال کیاجاتاتھا، اقبال نے بار بار یہ بات واضح کی کہ وہ جس معانی میں اس لفظ کااستعمال کر رہے ہیں، وہ بالکل مختلف اور متضاد ہے ۔ اقبال کے نظریہ خودی میں ایک مجاہد کاعزم اور استحکام عمل شامل ہے ، جو ایسی زندگی نہیں گزار سکتاجس میں خود زندگی کو نظرانداز کر دیاجائے ۔ اسرار خودی میں اقبال نے فکر، نظر اور کردار کی بعض اہم خصوصیات بیان کیں جو خودی کی نشونمااور ارتقاکے لیے ضروری ہیں۔ یہ امتیازی اوصاف عشق، فقرِ اللہ، جراتِ ایمانی اور اخلاقیات ہیں۔ اس تصور کی تخلیق کااصل سبب سیاسی پیچیدگیاں تھیں۔ وہ ملت کے اخلاقی انحطاط اور معاشرتی عیوب کو سیاسی غلامی کانتیجہ سمجھتے تھے ۔ اپنی نظم “مرگِ خودی” میں اقبال نے مشرق اور مغرب کی زبوں حالی کو زوالِ خودی کانتیجہ قرار دیاہے ۔ اقبال لکھتے ہیں:
خودی کی موت سے مغرب کااندروں بے نور
خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جذام
خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب
بد ن عراق و عجم کاہے بے عروق و عظام (9)
اقبال اس حقیقت کادعویٰ کرتے ہیں کہ صرف فکری یاخیالی مشاہدات انسانی زندگی کو عروج تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ متحرک قوت اور ردعمل انسانی زندگی اور مذہب کی اصل روح ہیں۔ اقبال اپنے خطبے کے دیباچے میں لکھتے ہیں:
قران مجید فکر کی بجائے عمل کی ترغیب دیتاہے ، مگر عام لوگوں کی فطرت میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے قلبی کیفیات، جن پر ان کے ایمان کی بنیاد رکھی گئی ہے ، کو اس طرح استعمال کریں کہ زندگی کے دیگر حالات یااپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر جذب کر لیں۔۔۔ مثبت تصوف نے ماضی میں اگرچہ مذہبی یاروحانی جذبے کے فروغ میں اہم کردار اداکیا، مگر جدید دور کے انسانی ذہن سے قطعی نااشناہے ۔(10)
خودی بغیر عمل اور تعبیر کی طاقت کے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ خودی کے بہت سے عناصر ہیں جو طاقت میں پنہاں ہیں۔ موجودہ دور میں مسلم امہ اپنی طاقت کھو رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کی خودی بھی مٹتی جارہی ہے ۔ لہٰذاخودی میں طاقت کاجزو شامل ہونایہ ثابت کرتاہے کہ نظریہ خودی سیاسی اہمیت رکھتاہے ۔ اقبال کاخیال ہے کہ جب تک ایک معاشرہ خودی کی بنیادوں پر قائم نہ ہو، وہ سیاسی اور اقتصادی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ ماضی اور آج کے دور میں اقبال کانظریہ خودی اپنی تمام تر سیاسی اہمیت کے ساتھ افاقی طور پر مسلمہ ہے ۔ آج کی تیز رفتار اور گلوبل معاشرت میں یہ تصور مزید اہمیت اختیار کر گیاہے ۔ موجودہ دور میں اقبال کاتصور خودی مثبت طرز پر اقوام کو مدد فراہم کرنے کی ترغیب دیتاہے ۔ یہ تصور افراد اور معاشرے کو یہ یقین دلاتاہے کہ وہ قوم کے فعال کارکن ہیں اور قوم کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار اداکر سکتے ہیں۔ تمام افراد کی خودی جب منظم ہو کر قوم کی خودی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اقبال اسے “بے خود ی” کانام دیتے ہیں۔ خودی کاتصور انفرادی روحانیت کے دائرے سے ماوراہو کر اپنے اثر و رسوخ کو سیاسی میدان تک پھیلادیتاہے ۔ سیاسی تناظر میں بے خود ی کو قوم کی بے لوث خدمت اور عظیم تر بھلائی کی طاقت سے تعبیر کیاجاتاہے ۔ یہ شہریوں کے درمیان اتحاد و یگانگت کو فروغ دیتاہے ۔
عصر حاضر کے پیچیدہ سیاسی منظرنامے میں “بے خود ی” کاتصور راہنماؤں کے لیے اتحاد، سماجی انصاف اور قوم کی بھلائی کے لیے ایک راہ نمااصول کے طور پر کام کر سکتاہے ۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ سیاسی طاقت کو بے لوث اور عظیم جذبے کے ساتھ استعمال کیاجاناچاہیے ۔
اقبال کی سیاسی تفہیم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک “مردِ مومن” یا”انسانِ کامل” کے نظریے کو بیان نہ کیاجائے ۔ فکرِ اقبال کایہ اہم موضوع ہے ۔ سیاسی تناظر میں اقبال کا”مردِ مومن” کاتصور ان کے فلسفے کاکلیدی پہلو ہے ۔ اقبال کامردِ مومن روحانی طور پر بیدار ہے ، جس کی جڑیں اسلامی اصولوں اور اقدار سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے اوصاف قوت، بصیرت، عمل اور فراست ہیں۔ یہی صفات دراصل سیرتِ رسولؐ میں بھی موجود تھیں۔ اپ کی سیرت و سنت کو راہ عمل بناکر ایک مومن اپنی تقدیر کو خود بدل سکتاہے ۔ ڈاکٹر عبد المعینی اقبال کے مردِ مومن کے بارے میں لکھتے ہیں:
وہ مجسمہ خودی ہے ۔ عرفانِ نفس کاعلم رکھتاہے ۔ اپنی شخصیت کے مسلسل ارتقامیں مگن ہے ۔ پوری کائنات اس کے ارتقائی کوششوں کی جولانگاہ ہے ۔ وہ زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے ۔ وہ اپنی حقیقت کاادراک ایمان بالغیب سے کرتاہے ، جو محبتِ الٰہی کاتقاضاہے ۔ وہ دیدارِ الٰہی سے سرشار ہے ۔ اس کی نماز اس طرح ہے کہ وہ خداکو دیکھ رہاہے اور خدااسے۔ اس کی تمام کوششوں کامقصد قربِ الٰہی کاحصول عطاکرتاہے۔(11)
بہت سے ناقدین کاخیال ہے کہ اقبال کاتصور “مردِ مومن” نیٹشے کے “سپرمین” سے مستعار لیاگیاہے اور دونوں میں مشابہت ہے ۔ اگرچہ کسی حد تک اقبال نیٹشے کے خیالات سے متاثر تھے ، لیکن حصولِ طاقت کاتصور نیٹشے اور اقبال کے نظریات میں مشترک ہے ۔ تاہم، اقبال کے لیے طاقت کانظریہ قران پر مبنی ہے ۔ دونوں فلسفیوں کے نظریات طاقت کے حصول کے حوالے سے متضاد ہیں، کیونکہ نیٹشے خداکاانکاری ہے۔
عصر حاضر میں اقبال کا”مردِ مومن” کاتصور گہری سیاسی اہمیت رکھتاہے ۔ ہنگامہ آرائی اور تصادم کے دور میں یہ تصور امید کی کرن ہے جو عالمی سیاسی سٹیج پر امن، انصاف اور ترقی کے لیے ایک مثال قائم کر سکتاہے ، کیونکہ اقبال کامردِ مومن محض مذہبی تقویٰ تک محدود نہیں بلکہ وہ اٹل ایمان، اخلاقی دیانت اور انصاف کاحامل ہے ، جو متحد قوت کے طور پر مذہبی تنوع کی حامل دنیامیں اتحاد کی علامت ہے ۔ عصر حاضر میں بین المذاہب ہم اہنگی کی کمی ہے ، لیکن اقبال کامردِ مومن رواداری اور بقائے باہمی کی ایک مثال قائم کر سکتاہے ۔ موجودہ دور کی سیاست اخلاقی دیانت سے محروم ہے اور مسلم امہ وطنیت کی جغرافیائی حدود میں بٹ چکی ہے ۔ اقبال کامردِ مومن سرحدی حدود سے بالاتر ہو کر بین المسلمین اتحاد کامحرک بن سکتاہے ۔ انصاف اور اخلاقی سالمیت کے لیے مومن کاعزم سفارتی مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتاہے ۔ اقبال کامردِ مومن مثبت سماجی تبدیلی کامحرک ہے اور ماحولیاتی انحطاط، سماجی ناانصافی اور معاشی عدم استحکام کے دور میں اہم عالمی مسائل حل کرنے میں قائد کاکردار اداکر سکتاہے ۔ عصر حاضر میں مردِ مومن کاتصور سیاسی اہمیت کاحامل ہے ۔ اقبال نے مردِ مومن کی خصوصیات کو اس شعر میں نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیاہے :
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (12)
مردِ مومن کے بعد اقبال کانظریہ “ملت” انتہائی اہمیت کاحامل ہے ۔ نسلی، نسبی اور علاقائی امتیازات سے بالاتر مسلمان جماعت کو اقبال نے “ملت” کانام دیا۔ اقبال کاعقیدہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ کی ہمہ گیری رنگ و نسل اور وطنیت کی قیود سے ماوراہے ، اور ملت کی اساس توحید اور رسالت کے مشترک عقائد پر مشتمل ہے ۔ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد عقیدہ توحید اور رسالت کی بنیاد پر اقوامِ عالم میں جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال نے بارہاامتِ مسلمہ کو دنیاکی بہترین قوم قرار دیااور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی کہ ملتِ اسلامیہ نے وسیع ترین اخوت کاتصور پیش کیا، جو کسی اور گروہ نے متعارف نہیں کرایا۔ اسلام کی حدود نہایت وسیع ہیں اور اس کی ماہیت لامحدود ہے ۔ اقبال نے اپنے مضمون “ملتِ بیضاپر ایک عمرانی نظر” میں ملتِ اسلامیہ کی ترکیبی ساخت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔
اقبال نے مذہب کو قومی زندگی کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام ہے جس میں ملت کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان اسلامی اصولوں سے پوری طرح واقف اور وابستہ نہ ہوں، ان کی قومی شناخت مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح انگریز اپنے وطن انگلستان سے اور جرمن اپنے جرمنی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا اصل رشتہ اسلام سے ہے۔ جب مسلمانوں نے دین کی اقدار اور روایات سے روگردانی کی، تو ان کی وحدت ٹوٹ گئی اور وہ منتشر ہو گئے۔ اقبال کا نظریۂ ملت محض ماضی کی بات نہیں، بلکہ آج کی دنیا میں بھی اس کی معنویت قائم ہے۔ جب مختلف تہذیبوں اور عقائد کا باہمی تصادم روز کا معمول بن چکا ہے، اقبال کا پیغام ہمیں باہمی احترام، ہم آہنگی اور روحانیت کی بنیاد پر ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آج کے مادی دور میں جہاں روحانی اقدار پس منظر میں چلی گئی ہیں، اقبال کی سوچ ہمیں دوبارہ روحانی ترقی کی جانب گامزن ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔
اقبال کاتصور ملت ایک لازوال اور قابل عمل نظریہ ہے جو اج دنیاکو درپیش بہت سے چیلنجوں کاحل پیش کرتاہے ۔ اقبال نے ہمیشہ اسلام کو سیاست کی بنیاد بتایاہے ۔ ملتِ اسلامیہ کی بقااور سربلندی کے لیے اسلام کے سنہری اصول راہنمائی فراہم کرتے ہیں، جو ملت اپنے فکر و عمل کی صلاحیتوں کو خداکے عطاکردہ حکم کے مطابق بروئے کار لائے گی۔ وہ یقیناعظمت اور قوت کاپیکر ہو گی جو سیاست قران اور حق پرستی کی بنیادوں پر استوار ہو گی، اور اس ملت کے ایوان ہمیشہ مستحکم بنیادوں پر قائم رہیں گے ۔
اقبال کے سیاسی نظریات میں قومیت کاتصور خاص اہمیت رکھتاہے ۔ یہ ایک ایسانظریہ ہے جس میں فکری تضاد کارنگ شامل ہے ۔ اقبال نے یورپ جانے سے پہلے ہندی قومیت پر مبنی نظمیں لکھیں جیسے ہمالہ، ترانہ ہندی اور نیاشوالہ وغیرہ۔ محکوم وطن کی نوحہ خوانی میں وہ خود بھی روئے اور اہلِ وطن کو بھی رلایا، مگر 1905ء سے 1908ء تک کاوقت یورپ میں گزارنے کے بعد جب اقبال وطن واپس آتے ہیں، تو ان کاجذبہ حب الوطنی مسلم قومیت میں بدل جاتاہے اور وہ یکدم نظریہ وطنیت اور قومیت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں۔ کیونکہ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران اہلِ مغرب کی انسان سوز سرگرمیوں کو اپنی تنقیدی نظروں سے دیکھااور ان سرگرمیوں کو عالم انسانیت کے لیے مہلک ترین اور تباہ کن قرار دیا۔
عصرِ حاضر کے حوالے سے دیکھاجائے تو اقبال کاقومیت کاتصور متضاد نہیں بلکہ متحرک اور ارتقاپذیر تصور تھاجو جدید دنیاکے سیاسی اور سماجی مسائل سے متعلق تھا۔ اقبال کاعقیدہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ کاسیاسی رویہ نظری اور عملی دونوں صورتوں میں مغربی اقوام سے جداگانہ ہے اور ہمیشہ جدائی رہنی چاہیے ۔ بانگِ درامیں اس خیال کو شعری صورت میں یوں بیان کیاہے :
ان کی جمیعت کاملک و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمیعت تری
دامنِ دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمیعت کہاں
اور جمیعت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی (13)
اقبال کی بصیرت نے یہ پہچان لیاتھاکہ عصر حاضر کے انسان کے ذہن و ضمیر پر قومیت کااثر اتناگہراہو چکاہے کہ یہ دیوی و دیوتاکی طرح اس کی ذہنی پرستش بن گئی ہے اور مذہبی صداقت کے لیے بقااور حیات کے امکانات کم ہوتے جارہے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں:
ان تازہ خداؤں میں بڑاسب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کاہے وہ مذہب کاکفن ہے (14)
اگرچہ اقبال عالمی مسلم قومیت کے حامی تھے ، لیکن انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی ضرورت کو بھی محسوس کیا۔ ان کے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کاایک الگ ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تشخص تھااور انہیں ایک علیحدہ سیاسی شناخت کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی مذہبی ازادی اور ثقافتی ورثے کاتحفظ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پاکستان کے قیام کے تصور کو پیش کیا، تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے دین اور ثقافت کے مطابق ازاد اور محفوظ زندگی گزارنے کاموقع مل سکے ۔ مسئلہ قومیت پر اقبال نے اپنی زندگی کے اخری ایام میں مولاناحسین احمد مدنی جیسے جید عالم سے اختلاف رائے کیااور علمی و منطقی بنیادوں پر اپنانظریہ واضح کیا۔
عصرِ حاضر میں قومیت کاتصور امت مسلمہ کے لیے انمول بصیرت پیش کرتاہے ، جس میں اتحاد، اخلاقی طرز، سماجی و اقتصادی ترقی اور عالمی برادری کے ساتھ فعال ربط شامل ہے ۔ اقبال کی سیاسی تفہیم میں پین اسلامزم کاذکر بھی نہایت ضروری ہے ۔ اقبال اتحاد عالم اسلامی تحریک سے گہراذہنی ربط رکھتے تھے ۔ انہوں نے اپنی نظم و نثر میں جمال الدین افغانی کی بہت مدح سرائی کی ہے ۔ اقبال اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
موجودہ دور میں اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کامستحق ہے تو وہ صرف جمال الدین افغانی ہے ۔ مصر، ایران، ترکی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو سب سے پہلے عبد الوہاب نجدی اور پھر جمال الدین افغانی کاذکر کرناہوگا۔(15)
جاوید نامہ میں اقبال نے جمال الدین افغانی کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے اپنی تصنیف کاایک بڑاحصہ وقف کیاکیونکہ اقبال کے ذہن میں اسلام کاروشن مستقبل عالمگیر ملت کی صورت میں ممکن تھا۔ اقبال اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کی عالمی اخوت سے انحراف، قرانی نظریہ حیات کے بنیادی اصولوں سے انحراف کے مترادف ہے ۔ یہ امر دلچسپی کاباعث ہے کہ اقبال نے اسلام کی ہمہ گیر اخوت کی نشر و اشاعت کے لیے زبان و قلم سے مسلسل کوششیں کیں، لیکن انھوں نے “پین اسلامزم” کی مخصوص اصطلاح کی تردید کی۔ اس بات کے شواہد قاضی احمد میاں احمد کی تصنیف سے ملتے ہیں، جس میں وہ رقمطراز ہیں:
“اقبال نے اس اصطلاح کی ترد ید کرد ی ہے ۔ ان کے نزد یک اس لفظ کاکوئی مفہوم نہیں”۔(16)
اقبال مسلم ممالک کے درمیان ایسے اتحاد کے پُر زور حامی تھے جو مسلمانوں کو مختلف ممالک میں رہنے کے باوجود ایک وحدت میں بدل دے ۔ نظریہ قومیت سے بچاکر ملت اسلامیہ کو ہمہ گیری کی راہ پر گامزن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کی بصیرت نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یورپ کی اقوام مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی مسلم ریاستوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ 1908ء کے بعد اقبال کو یقین ہوگیاکہ عصر حاضر میں وطنی قومیت سمِ قاتل ہے ، خاص طور پر اہل اسلام کے لیے جن کے دینی اصول اس کے برعکس ہیں۔ اگر پین اسلامزم کامفہوم اتحاد بین المسلمین، انسانی معاملات میں قرانی تعلیمات کانفاذ، اور مسلمانوں میں بے عملی اور جمود کو ختم کرنے کے لیے اجتہاد کے ذریعے غیر اسلامی رسومات کاخاتمہ ہو، تو اقبال اپنی پوری زندگی اس محاذ پر سرگرم رہے اور اپنے شعری اور نثری مجموعوں میں مسلمانوں کی راہنمائی کرتے رہے ۔ عصر حاضر میں پین اسلامزم کاتصور مثبت تبدیلی کی صلاحیت رکھتاہے جس سے امت مسلمہ عالمی معاملات میں زیادہ اہم کردار اداکر سکتی ہے۔ اختلافات سے بالاتر ہو کر عالمی چیلنجوں سے نمٹنے ، د قیانوسی تصورات کامقابلہ کر کے اور اقتصادی تعاون کو فروغ دے کر یہ تصور ایک مضبوط اور زیادہ بااثر اسلامی دنیاکے لیے راستہ ہموار کر سکتاہے ۔
اگر سیاسی نظاموں کی بات کی جائے تو اقبال نے دو بڑے مغربی نظاموں پر تفصیلی افکار پیش کیے ، جن میں جمہوریت اور اشتراکیت شامل ہیں۔ اقبال کی سیاسی تفہیم ان نظاموں پر بحث کے بغیر ادھوری ہے ۔ لہٰذاجب جمہوریت پر نظر ڈالی جائے تو اقبال مغربی جمہوریت کے بڑے ناقد تھے ۔ ان کے مطابق مغربی جمہوریت انگریزوں کی مکاری اور فریب کے سواکچھ نہیں۔ انگریزوں نے اپنے نوآبادیاتی نظام کو مضبوط اور جائز قرار دینے کے لیے یہ جواز پیش کیاکہ دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت دراصل جمہوریت کے فروغ کی ایک کوشش ہے اور پسماندہ ممالک کی غربت کو ختم کرنے کی طرف پیش رفت ہے ۔ اسی لیے علامہ اقبال جمہوریت کو قابل نفرت جانتے ہیں اور اسے دیگر سیاسی نظاموں یعنی مطلق العنان شہنشائیت، آمریت اور ملوکیت کے مماثل قرار دیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شیراز زیدی لکھتے ہیں:
مغربی جمہوریت دراصل ملوکیت کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ۔ جب محکوموں میں بیداری اتی ہے اور وہ حکومت میں اپناحصہ طلب کرتے ہیں تو چالاک حکمران انھیں خوش کرنے کے لیے ایک آئین ساز مجلس بنادیتے ہیں، لیکن انتخاب کے اصول اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ جاگیردار اور وڈیرے ہی اس میں شامل ہو سکیں تاکہ حکومت کے مفادات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے ۔ علامہ اقبال کے نزدیک ایسی جمہوریت حکمرانوں کی ساحری ہے ۔(17)
اقبال کے نزدیک جمہوریت صرف ایک حکومت کانظام نہیں بلکہ ایک طرز ِزندگی ہے جو اسلامی نظریات کی تفہیم اور اطلاق سے ممکن ہے ۔ ان کاخیال تھاکہ حقیقی جمہوریت کو انصاف، مساوات اور احتساب کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے ۔ ان کا تصور جمہوریت چند ایسے تصورات میں سے ہے جن میں اخرت تک استقلال و استقراء کی حالت پائی جاتی ہے ۔ اقبال پختہ خیالی کے حامل تھے اور اپنے زمانے میں بھی جمہوری طرز حکومت کو اسلامی روح کے مطابق ناگزیر سمجھتے رہے ۔ اقبال اسلامی نظام میں روحانی اور اخلاقی جمہوریت کی خصوصیات پاتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر کو ایسے عناصر کاامتزاج ثابت کرتے ہیں جو بدعنوانی اور مفاد پرستی کے عیب سے پاک ہیں۔ “اسلام کااخلاقی و سیاسی نصب العین” اقبال کاوہ پہلامقالہ ہے جو جمہوریت کے حوالے سے ان کے افکار کے صحیح ادراک اور تفہیم کے لیے نہایت مددگار ہے ۔ اقبال لکھتے ہیں:
۔۔۔ایسی ملت کے لیے بہترین طرزِ حکومت جمہوریت ہی ہوگی جس کامقصد یہ ہو کہ جتناممکن ہو، ازادی فراہم کر کے انسان کو اپنی فطرت کے تمام امکانات کو ترقی دینے کاموقع دیاجائے ۔ اسلام کاسب سے اہم پہلو، بحیثیت ایک سیاسی نصب العین، جمہوریت ہے ۔(18)
دیگر سیاسی افکار کی طرح اقبال نے نظریہ اشتراکیت کو سنجیدگی سے اپنی فکر کاموضوع بنایااور ایک مخصوص نقطہ نظر قائم کیا۔ انہوں نے اشتراکیت، کارل مارکس اور سرمایہ داری کے موضوع پر نظمیں لکھیں جن میں اس نظریہ کانہایت مدبرانہ جائزہ پیش کیاگیاہے ۔ اقبال کے مطابق تمام سیاسی نظاموں کے پس پردہ معاشی عوامل ہی کارفرماہوتے ہیں، اور ان عوامل کی بدولت ہی سرمایہ داری اور اشتراکی نظام وجود میں آتے ہیں۔
اشتراکیت سے اقبال کی دلچسپی انقلابِ روس سے شروع ہوئی۔ وہ ایک جدید اور انقلابی شاعر تھے ۔ بالِ جبریل اور دیگر تصانیف میں انہوں نے اتنی پرجوش نظمیں لکھیں کہ انہیں بلاتکلف اشتراکی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اقبال اشتراکیت کے بعض بنیادی نکات سے شدید اختلاف رکھتے تھے ۔ اقبال نے یورپ میں سرمایہ داری نظام کی مکاری اور کھوکھلاپن کھلی انکھوں سے دیکھااور اس نظام کو سخت ناپسند کیاجس میں سرمایہ دار اور مزدور کے طرز ِزندگی میں بہت فرق پایاجاتاہے ۔ اقبال مزدوروں کے ہمدرد اور غمگسار ہیں اور ہر اس طبقے کے مخالف ہیں جو انسان اور انسانیت کو نقصان پہنچائے ۔ اقبال خضرِ راہ میں لکھتے ہیں:
اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
شاخِ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات!
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات ! (19)
اگرچہ اقبال نے سرمایہ داری نظام کو ناپسند کیااور اشتراکی نظام میں مزدوروں سے ہمدردی کو پسند کیا، مگر اس سے یہ غلط فہمی پیداہوئی کہ اقبال کمیونسٹ تھے ۔ لیکن تحقیق نے یہ ثابت کیاکہ اقبال نے اسلام کادم کبھی نہیں چھوڑااور بہت مدبرانہ طریقے سے اشتراکیت کے صرف ان عناصر کو قابلِ تحسین جاناجو اسلامی طرز سے ہم اہنگ تھے ۔ خاص طور پر دولت کی منصفانہ تقسیم کانظریاتی پہلو اشتراکیت سے دلچسپی کاباعث بنا۔ اگرچہ عملی طور پر اشتراکی نظام اس پرکشش نظریے کو نافذ کرنے میں ناکام رہا۔ فکراقبال تقاضاکرتی ہے کہ معاشرے میں موجود اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اسلام کامعاشی نظام اپنایاجائے ۔اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے زکوٰۃ کانصفانہ نظام متعارف کروایاہے ۔ اقبال اس بات پریقین رکھتے تھے کہ محض مادی وسائل حقیقی اور روحانی خوشی کاضامن نہیں بن سکتے ، بلکہ معاشی اور روحانی پہلوؤں کا بھی ہم آہنگ ہوناضروری ہے ۔ عصر حاضر میں اقبال کے سیاسی نظریات عصری مسائل سے نمٹنے کاآلہ کار بن سکتے ہیں۔
جدید دنیاعدم مساوات، ماحولیاتی مسائل، سماجی و فلاحی سہولتوں کی کمی، اخلاقی اقدار میں تنزلی، مفاد پرستی، طاقت کابے جااستعمال اور اس طرح کے بہت سے مسائل کاسامناکر رہی ہے ، جیساکہ اقبال اپنی نظم “عصر حاضر” میں لکھتے ہیں:
یہ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی
اس زمانے کی ہوارکھتی ہے ہر چیز کو خام (20)
اقبال کے سیاسی نظریات ایک صدی گزرنے کے باوجود بھی اس دور سے ہم آہنگ ہیں اور شاید آنے والاہر زمانہ اقبال کو اپنے دور کے مطابق پائے گا، کیونکہ اقبال کے سیاسی نظریات جیسے کہ حاکمیت و قوت، اجتہاد، خودی و بے خودی، مرد مومن، ملت، قومیت، پین اسلامزم، جمہوریت اور اشتراکیت ایسے سیاسی نظریات ہیں جو عصر حاضر میں بھی اپنی افادیت اور مطابقت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کاہر تصور دوسرے تصور سے مربوط ہے ۔ اقبال یہ تقاضاکرتے ہیں کہ ایسامرد مومن جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے قوت و طاقت کامثبت استعمال کرے ، خودی کی صفت سے متصف ہو، اجتہاد کاراستہ اختیار کر کے کامیابی و خوشحالی کی نئی راہیں دریافت کرے ، شاہین کی نظر اور پرواز کاجذبہ رکھتاہو، جغرافیائی اور نسلی تعصبات سے پاک ہو، امت مسلمہ کی امامت کافریضہ اداکر سکے ، اور تمام دنیاکے مسلمانوں کے رہنماکی حیثیت سے بین المسلمین اتحاد کو برقرار رکھ سکے ۔
عصر حاضر کے سیاسی نظام شدید بگاڑ کاشکار ہیں۔ ہر ملک اپنے سیاسی نظام میں مختلف تجربات کرتانظر آتاہے ، جبکہ اقبال نے سو سال پہلے اسلامی جمہوری نظام متعارف کرواکر ایک کامل سیاسی نظریہ پیش کیاجو نہ تو مارکسیت سے ماخوذ ہے اور نہ ہی کسی دیگر مغربی نظام سے اخذ کیاگیاہے ۔ عصر حاضر میں اقبال کو عصری تناظر میں سمجھاجائے تو ان کے سیاسی نظریات جدید دور میں بھی اپنی تازگی برقرار رکھتے ہیں اور جدید دنیاکے مسائل حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔
اقبال براہ راست سیاست میں زیادہ فعال نہیں رہے ، لیکن انہوں نے آل انڈیامسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے ذریعے مسلمانوں کی سیاسی راہنمائی کی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اپناقائد مانتے تھے اور ان کی قیادت کے زبردست حامی تھے ۔ ان کاسیاسی شعور ایک ایسی سوچ کاعکاسی کرتاہے جو نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی مسائل کا نہ صرف ادراک رکھتی تھی بلکہ ان کے حل کے لیے قابلِ عمل تجاویز بھی پیش کرتی تھی۔ ان کے افکار آج بھی ہمارے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
حوالہ جات
- علامہ اقبال، “کلیاتِ اقبال ارد و”، اقبال اکاد می پاکستان، لاہور، 2015ء، ص487
- پروین شوکت علی، ڈاکٹر، “اقبال کافلسفہ سیاسیات”، مترجم ریاض الحق عباسی، اسد پبلی کیشنز، لاہور، ص124-125
- ایضا، ص141
- علامہ اقبال، “کلیاتِ اقبال ارد و”، ص665
- ایضا، ص714
- محمد عثمان، پروفیسر، “فکراسلامی کی تشکیلِ نو-خطبات کاایک مطالعہ”،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، 1987ء، ص 152-153
- علامہ اقبال، “کلیاتِ اقبال ارد و”، ص635-636
- ایضا، ص534
- علامہ اقبال،”ضربِ کلیم”، شیخ غلام علی اینڈسنزلاہور، 1976ء، ص80
- جاوید اقبال، ڈاکٹر”خطباتِ اقبال۔تسہیل وتفہیم”، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، 2008ء، ص596
- عبد المغنی، ڈاکٹر، “اقبال کانظریہ خود ی”، بک کارنرجہلم، 2016، ص260
- علامہ اقبال، “کلیاتِ اقبال ارد و”، ص285
- ایضا، ص277
- ایضا، ص187
- پروین شوکت علی، ڈاکٹر، “اقبال کافلسفہ سیاسیات”، ص312
- احمد میاں اختر،قاضی، “اقبالیات کاتنقید ی جائزہ”، اقبال اکاد می پاکستان، لاہور، 1962ء، ص142
- شیراززید ی، ڈاکٹر، “سامراجیت پراقبال کی تنقید “،سعید پبلی کیشنزکراچی، 2015ء، ص73
- علامہ اقبال ، ڈاکٹر، “مقالاتِ اقبال”، مرتبہ سید عبد الواحد معینی، محمد عبد اللہ قریشی، القمرانٹرپرائز اردوبازار لاہور، 2011ء، ص77
- علامہ اقبال، “بانگِ د را”، شیخ غلام علی اینڈسنزلاہور، 1989ء، ص262
- علامہ اقبال، “کلیاتِ اقبال ارد و”، ص594