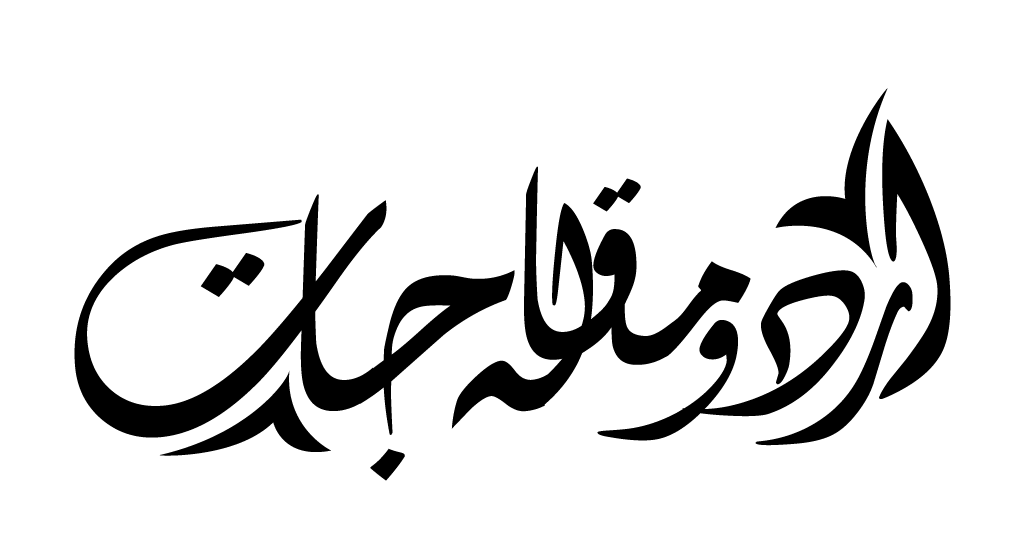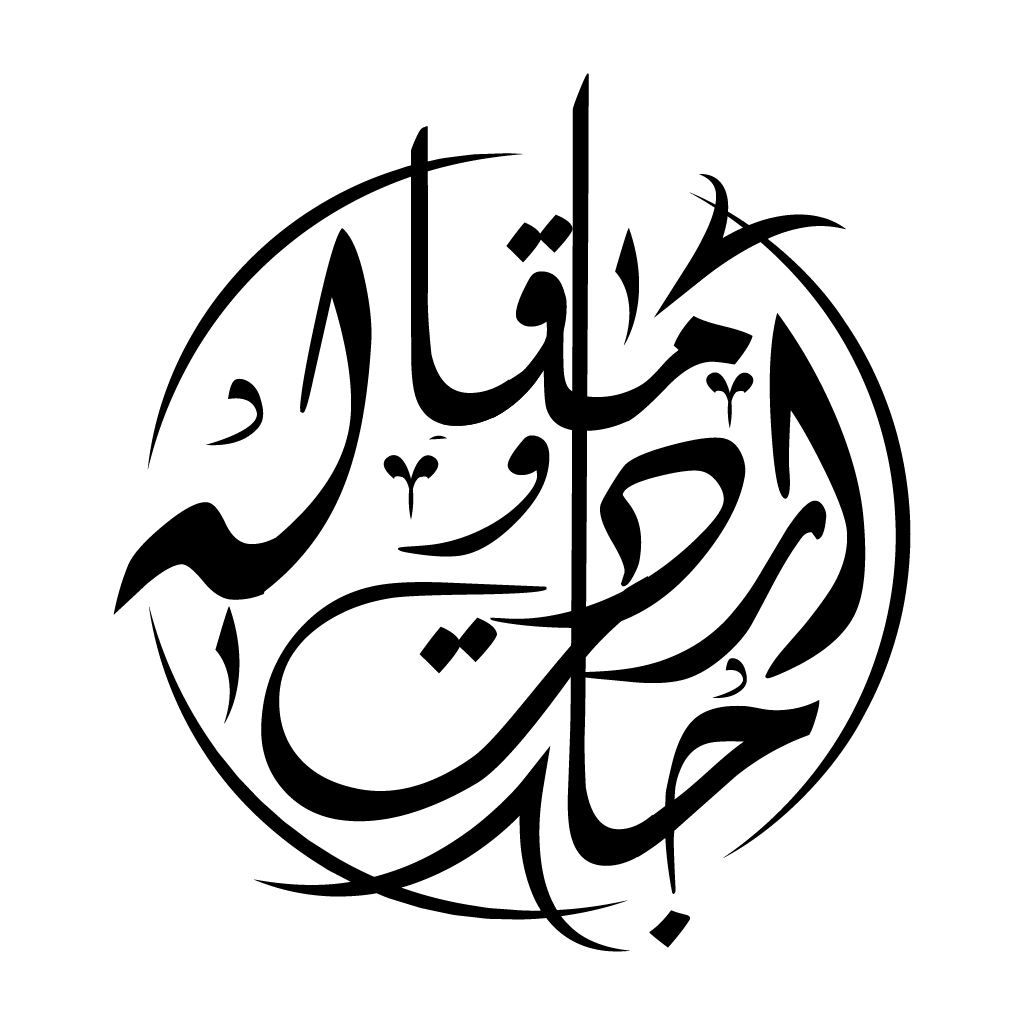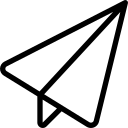اساطیر سے مراد قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں کی وہ روایتی داستانیں ہیں جو دیوتاؤں، ہیروز، تخلیقِ کائنات اور فطری مظاہر سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں کسی قوم کے بنیادی عقائد، اقدار اور تہذیبی ورثے کی عکاس ہوتی ہیں۔ شاعری میں اساطیر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ شاعر کو ایک علامتی زبان فراہم کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ پیچیدہ انسانی جذبات، سماجی مسائل اور فلسفیانہ خیالات کو مختصر مگر موثر انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ اساطیری کردار اور واقعات شاعری کو گہرائی اور وسعت عطا کرتے ہیں، جیسے یونانی اسطورہ “پرومیتھیس” ظلم کے خلاف بغاوت کی علامت بن جاتی ہے یا “لیلیٰ مجنوں” کی داستان ناکام محبت کی استعارہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اساطیر کے استعمال سے شاعری نہ صرف ادبی حسن حاصل کرتی ہے بلکہ یہ قدیم و جدید کے درمیان ایک پل کا کام بھی کرتی ہے، جس سے کلام کو عالمگیریت اور دوام ملتا ہے۔ اقبال، فیض، راشد اور جون ایلیا جیسے جدید شعرا نے اساطیر کو استعمال کر کے اپنی شاعری کو فکری گہرائی اور فنکارانہ بلندی عطا کی ہے۔
ادب میں اساطیر کی اہمیت بنیادی طور پر ان کے علامتی اور تہذیبی کردار میں پوشیدہ ہے۔ اساطیر محض قدیم قصے کہانیاں نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے اجتماعی لاشعور کا ایک اہم حصہ ہیں جو ادب کو گہرائی، وسعت اور دوام عطا کرتی ہیں۔ یہ ادبی تخلیق میں ایک ایسی علامتی زبان تشکیل دیتی ہیں جو مصنف کو پیچیدہ انسانی تجربات، جذبات اور سماجی حقائق کو انتہائی مختصر مگر موثر انداز میں پیش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اساطیر کے ذریعے ادب میں وقت اور مکان کی حدود کو عبور کیا جاتا ہے، جس سے تخلیق کو ایک عالمگیر پہنائو حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً یونانی اسطورہ “سیزیفس” جدید ادب میں انسان کی بے مقصد جدوجہد کی علامت بن جاتی ہے، یا پھر “لیلیٰ مجنوں” کی داستان محبت کی ناکامی کے ساتھ ساتھ روحانی عشق کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ اساطیر ادب کو تہذیبی تسلسل سے جوڑتی ہیں، جس سے قاری کو اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے سے رشتہ استوار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جدید اردو ادب میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ن م راشد اور بانو قدسیہ جیسے ادیبوں نے اساطیر کو نئے تناظر میں استعمال کرکے اپنے کلام کو فکری اعتبار سے زیادہ توانا اور فنکارانہ اعتبار سے زیادہ موثر بنایا ہے۔ اساطیر کا یہی وہ کثیر الجہتی کردار ہے جو انہیں ادب کے لیے ناگزیر بناتا ہے۔
بیسویں صدی کی اردو شاعری میں اساطیری عناصر کا استعمال ایک اہم ادبی اور فکری رجحان کے طور پر ابھرا، جس نے شاعری کو محض جذباتی اظہار سے نکال کر تہذیبی، علامتی اور فکری جہات سے ہمکنار کیا۔ اساطیر (Mythology) سے مراد وہ قدیم داستانیں، کہانیاں اور علامات ہیں جو مختلف تہذیبوں، مذاہب اور قوموں میں رائج رہی ہیں اور جن میں دیوی دیوتاؤں، مافوق الفطرت کرداروں، ازلی کشمکش، اور کائناتی توازن کی کہانیاں شامل ہوتی ہیں۔ اردو شاعری میں ان عناصر کا استعمال آغاز سے موجود تھا، مگر بیسویں صدی میں جدیدیت، مابعد جدیدیت، استعماریت کے خلاف ردِ عمل، اور تہذیبی شناخت کے مباحث کے ساتھ اساطیری حوالوں کا استعمال فنکارانہ علامتوں، فکری گہرائی، اور لسانی تجربے کے طور پر نمایاں ہونے لگا۔
بیسویں صدی کے آغاز میں علامہ اقبال نے اساطیر کو فلسفیانہ اور روحانی پس منظر میں برتا۔ اگرچہ انہوں نے مغربی فلسفے، اسلامی تاریخ، اور قرآنی تلمیحات کو ترجیح دی، لیکن ان کے ہاں فرشتے، ابلیس، آدم، جبرئیل اور خضر جیسے کردار اساطیری حیثیت رکھتے ہیں جنہیں وہ فکر انگیز علامتوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ابلیس محض شیطان نہیں، بلکہ طاقت، مادیت، اور خود غرضی کی علامت بن کر سامنے آتا ہے، جبکہ خضر رہنمائی، وجدان اور روحانی بصیرت کی علامت بن جاتے ہیں۔
اساطیری حوالوں کا وسیع استعمال جدید اردو شاعری میں خاص طور پر ن م راشد اور میراجی کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ن م راشد نے ایرانی، یونانی اور ہندی اساطیر کو علامتی اور فکری تناظر میں استعمال کیا۔ ان کی نظموں میں زرتشت، اہرمن، نمرود، سامری، نانک، گوتم، اشوک، اور ابلیس جیسے کرداروں کو بطور تمثیل استعمال کر کے طاقت، تضاد، جنسی جبلت، اور روحانی شکست وریخت کے مسائل بیان کیے گئے۔ ان کا اسلوب اور لغت کلاسیکی اساطیر سے متاثر ہونے کے باوجود مکمل طور پر جدید فکری سیاق رکھتی ہے۔ اسی طرح میرaji نے ہندوستانی دیومالا اور یونانی اساطیر کو اپنی داخلی کائنات کی ترجمانی کے لیے استعمال کیا۔ ان کے ہاں رام، سیتا، رادھا، کرشن، سکندر، اپسرا، وشنو جیسے کردار محض قصے نہیں، بلکہ نسوانیت، جنس، محبت، حسن اور بے یقینی جیسے پیچیدہ موضوعات کی علامت بن کر نمودار ہوتے ہیں۔
فیض احمد فیض کی شاعری میں اگرچہ اساطیری حوالے بہت زیادہ نہیں، مگر جب بھی آتے ہیں، تو وہ ظلم و استحصال کے خلاف تاریخی شعور کی بیداری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فیض نے فرات، کربلا، حور، عرش و فرش جیسے قرآنی اور اسلامی اساطیری استعاروں کو انقلاب، جدوجہد، اور اجتماعی شعور سے جوڑا۔
اسی طرح شہریار، انور شعور، احمد مشتاق، آفتاب اقبال شمیم اور دیگر جدید شعراء نے بھی اساطیر کو وقت کی پیچیدگیوں، تہذیبی الجھنوں اور انسانی لاشعور کی تمثیل کے طور پر برتا۔ بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں، جب اردو شاعری میں مابعد جدید رویے ابھرے، تو اساطیری کردار محض ثقافتی ورثے کے نمائندے نہیں رہے بلکہ وہ شناخت کے بحران، تہذیبی زوال، اور وقت کی بے معنویت کے استعارے بن گئے۔
خلاصہ یہ کہ بیسویں صدی کی اردو شاعری میں اساطیری عناصر کا استعمال محض تلمیحات یا داستانوں کی یاد دہانی کے لیے نہ تھا، بلکہ ان میں انسانی وجود، نفسیات، تاریخ، اور تہذیب کا فکری تجزیہ پنہاں تھا۔ اساطیر نے شاعری کو کثیر الجہتی بنایا، اس میں کائناتی معنویت اور تہذیبی تناظر داخل کیا، اور قاری کو محض جذبات کے دائرے میں مقید رکھنے کے بجائے فکری اور جمالیاتی مکاشفے کے سفر پر روانہ کیا۔ یہ رجحان آج کی اردو شاعری میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اساطیر محض ماضی کا قصہ نہیں بلکہ انسانی لاشعور کی مستقل صدائے بازگشت ہے۔