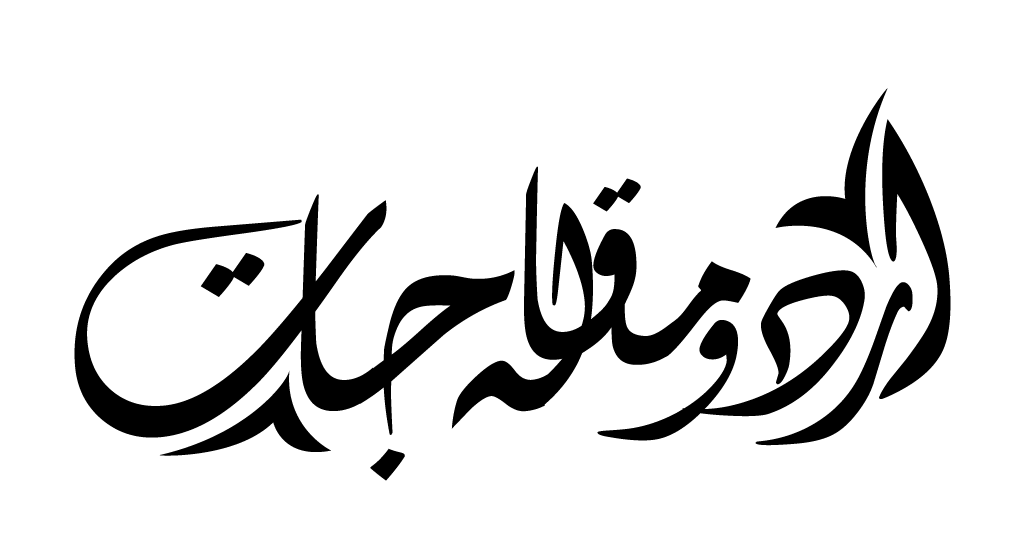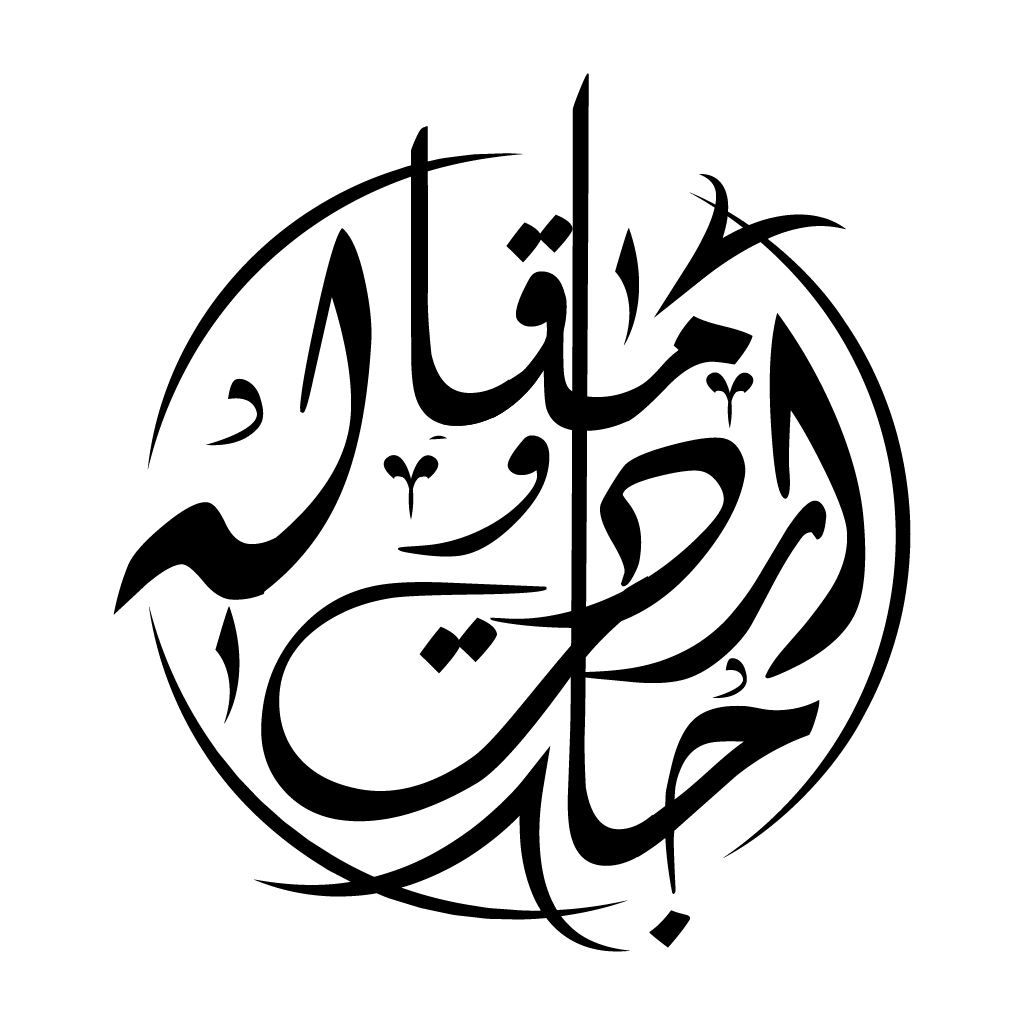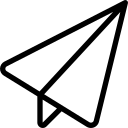اقبال کا شمار اردو شاعری کے ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کلام میں کائنات، قدرت، انسان، روحانیت، سیاست، تہذیب اور معاشرت کے متنوع پہلوؤں کو یکجا کیا ہے۔ فطرت نگاری ان کے کلام کا ایک اہم اور فکری پہلو ہے۔ اقبال کی شاعری میں فطرت محض مناظر کی تصویر کشی نہیں بلکہ ایک فکری، روحانی اور علامتی تجربہ ہے۔ اقبال نے پہاڑ، دریا، چاند، سورج، پرندے، درخت، اور بادل جیسے عناصر کو انسانی اور تہذیبی ارتقا سے جوڑ کر معنویت عطا کی ہے۔ ان کے ہاں فطرت نگاری ایک روحانی بیداری اور فلسفیانہ پیغام کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ اس کے برعکس ان کے ہم عصر شاعر سر عبدالقادر یا مولانا ظفر علی خان جیسے شعرا کی فطرت نگاری زیادہ تر روایتی، منظر کشی کی حد تک محدود نظر آتی ہے، جس میں احساسات و جذبات کی عکاسی تو ہے، لیکن اقبال کی طرح ایک فلسفیانہ عمق نہیں۔
اقبال کی فطرت نگاری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اردو کلام، خصوصاً “بانگِ درا”، “بالِ جبریل”، اور “ضربِ کلیم” کے اشعار کو فکری اور علامتی سطح پر پرکھا جائے۔ “بانگِ درا” کے نظم “ہمالہ” میں پہاڑ کی عظمت، جلال اور دوام کو انسانیت کی وحدت اور استقامت سے تعبیر کیا گیا ہے:
اے ہمالہ! اے فصیلِ کشورِ ہندوستاں
چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں
یہ صرف ایک قدرتی منظر کا بیان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیبی اور قومی علامت ہے۔ یہاں ہمالیہ کی بلندیاں ایک قوم کی خودی، حوصلے اور تاریخ کی علامت بن جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک فطرت کا مشاہدہ انسان کے باطن سے جڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں:
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے
فطرت کی گہرائیوں کو دریافت کرنے کے لیے خودی کا شعور ناگزیر ہے۔ چنانچہ فطرت نگاری اقبال کے ہاں داخلی خودی کے ادراک سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کی ایک اور نظم “طلوع اسلام” میں سورج کے طلوع ہونے کا منظر محض ایک قدرتی عمل نہیں بلکہ ایک اسلامی نشاۃِ ثانیہ کی علامت ہے۔
اقبال کی فطرت نگاری میں اکثر اشیاء اور مظاہر کائنات متحرک نظر آتے ہیں۔ پرندے، ستارے، دریا، پہاڑ، شفق، شبنم، بجلی، آندھیاں — سب ایک حرکت، ایک مقصد، ایک فلسفہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نظم “ایک پرندے کی فریاد” میں ایک قید پرندہ فطرت سے جدا ہو کر اپنا نوحہ بیان کرتا ہے۔ یہ محض ایک مظلوم پرندے کی کہانی نہیں بلکہ آزادی، جبلت، فطری وجود اور انسان کی ازلی تمنا کا استعارہ ہے۔
اس کے مقابلے میں ہم اگر مولانا ظفر علی خان کی فطرت نگاری پر نظر ڈالیں تو وہ زیادہ تر قدرتی مناظر کی جمالیاتی تصویر کشی تک محدود رہتی ہے۔ ان کے اشعار میں صبح کی روشنی، ندی کے بہاؤ، چاندنی رات، یا گلوں کی بہار کا ذکر تو ہے، مگر ان عناصر کو اقبال کی طرح ایک تہذیبی یا فلسفیانہ علامت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ان کے اشعار میں درج ذیل منظر عام فطرت نگاری کے عمدہ مظاہر تو ہیں مگر اس میں اقبال کی معنویت اور تمثیل نہیں ملتی:
گلوں میں رنگ ہے، خوشبو ہے، بہاریں ہیں بہت
پر اقبال کی نظر میں ہے کڑی تنقید کا رخ
یعنی ظفر علی خان کی فطرت نگاری میں فکری گہرائی کم جبکہ جمالیاتی دلکشی زیادہ نمایاں ہے۔ اقبال کے برعکس ان کے ہاں فطرت مظاہر کی حیثیت سے موجود ہے، نہ کہ علامات یا تمثیلات کے طور پر۔
اقبال کے ہاں فطرت ایک زندہ اور فعال قوت ہے، جو انسان کو فکر، حرکت، بیداری اور خودی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ان کے کلام میں فطرت کا تصور صرف فطری مظاہر تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل فکری و روحانی نظام کا حصہ ہے۔ ان کی نظم “مسجد قرطبہ” میں دریا، روشنی، اور وقت جیسے فطری مظاہر کو ایک تاریخی، ثقافتی، اور فکری تناظر میں برتا گیا ہے۔ اس نظم میں فطرت کی علامتیں تاریخ اور ملت کی تشکیل میں کردار ادا کرتی ہیں:
دریا بھی وہی، موج بھی وہی، زور بھی وہی
ہے دل کو مگر دیکھ کے آتا نہیں جوش
یہاں فطرت ایک داخلی اضطراب، تاریخ کی بے حسی، اور روحانی خلا کا آئینہ ہے۔ اقبال کا قاری جب ان کی فطرت نگاری کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ صرف حسنِ کائنات سے محظوظ نہیں ہوتا بلکہ ایک فکری اور تہذیبی پیغام بھی حاصل کرتا ہے۔ اقبال کے یہاں فطرت کو خدا کا مظہر، انسان کی خودی کا آئینہ اور ملت کے ارتقاء کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔
اب اگر ہم سر عبدالقادر جیسے ہم عصر شعرا کی شاعری کا جائزہ لیں تو ان کی فطرت نگاری عام طور پر جمالیاتی و رومانی رجحان کی حامل نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار میں صبح کا منظر، چاندنی رات، کوئل کی آواز اور پھولوں کی بہار کا ذکر تو خوبصورتی سے کیا گیا ہے، لیکن اس میں فکر و فلسفہ کا وہ رنگ نہیں جو اقبال کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر:
صبح دم جب شبنمِ تازہ گرتی ہے گلوں پر
دل کو ایک بے نام سی راحت سی ہوتی ہے
یہ منظر یقینی طور پر دلکش ہے، مگر اس میں کوئی فکری تحریک، کوئی علامتی پہلو، یا تہذیبی تناظر نہیں ہے۔
اقبال کے ہاں فطرت نگاری میں ایک اور اہم پہلو علامت نگاری ہے۔ ان کے ہاں عقاب، شاہین، پہاڑ، شعلہ، شفق، اور بجلی — یہ سب استعارہ بن جاتے ہیں کسی بڑے مقصد یا فلسفے کے لیے۔ شاہین ان کے ہاں خودی، بلندی، جرات، اور انفرادیت کی علامت ہے۔ اسی طرح بجلی عمل، تحرک اور انقلابی سوچ کی علامت بنتی ہے۔ ان کے ہاں مظاہر فطرت محض خارجی مظاہر نہیں بلکہ ان کی شاعری کا داخلی جوہر بن جاتے ہیں۔
اقبال کی فطرت نگاری کو جب ہم علامت، استعارہ، فلسفہ، اور فکری تحریک کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم عصر شعرا سے ایک منفرد اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت نگاری جمالیاتی حسن کے ساتھ ساتھ فکری و روحانی بلندی کی حامل ہے، جبکہ دیگر شعرا کی فطرت نگاری عمومی طور پر جمالیاتی یا جذباتی حدود میں رہتی ہے۔
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی فطرت نگاری محض کائناتی مظاہر کی عکاسی نہیں بلکہ ان مظاہر کو ایک فکری، روحانی، اور تہذیبی پیغام میں ڈھالنے کی شعوری کوشش ہے۔ ان کے کلام کا یہ پہلو انہیں اردو شاعری میں ایک انوکھا اور بے مثال مقام عطا کرتا ہے۔ ان کے ہم عصر شعرا فطرت سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسے اقبال کی طرح فلسفہ، تاریخ، اور خودی کی روشنی میں پیش نہیں کرتے۔ یہی فرق اقبال کی فطرت نگاری کو نہ صرف منفرد بناتا ہے بلکہ اردو شاعری کے دامن کو وسعت اور فکری گہرائی بھی عطا کرتا ہے۔