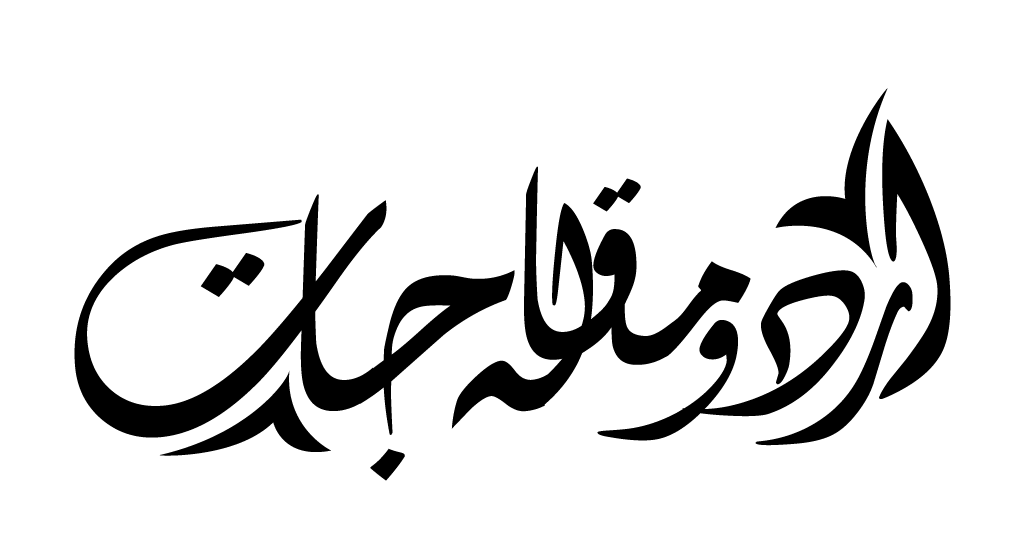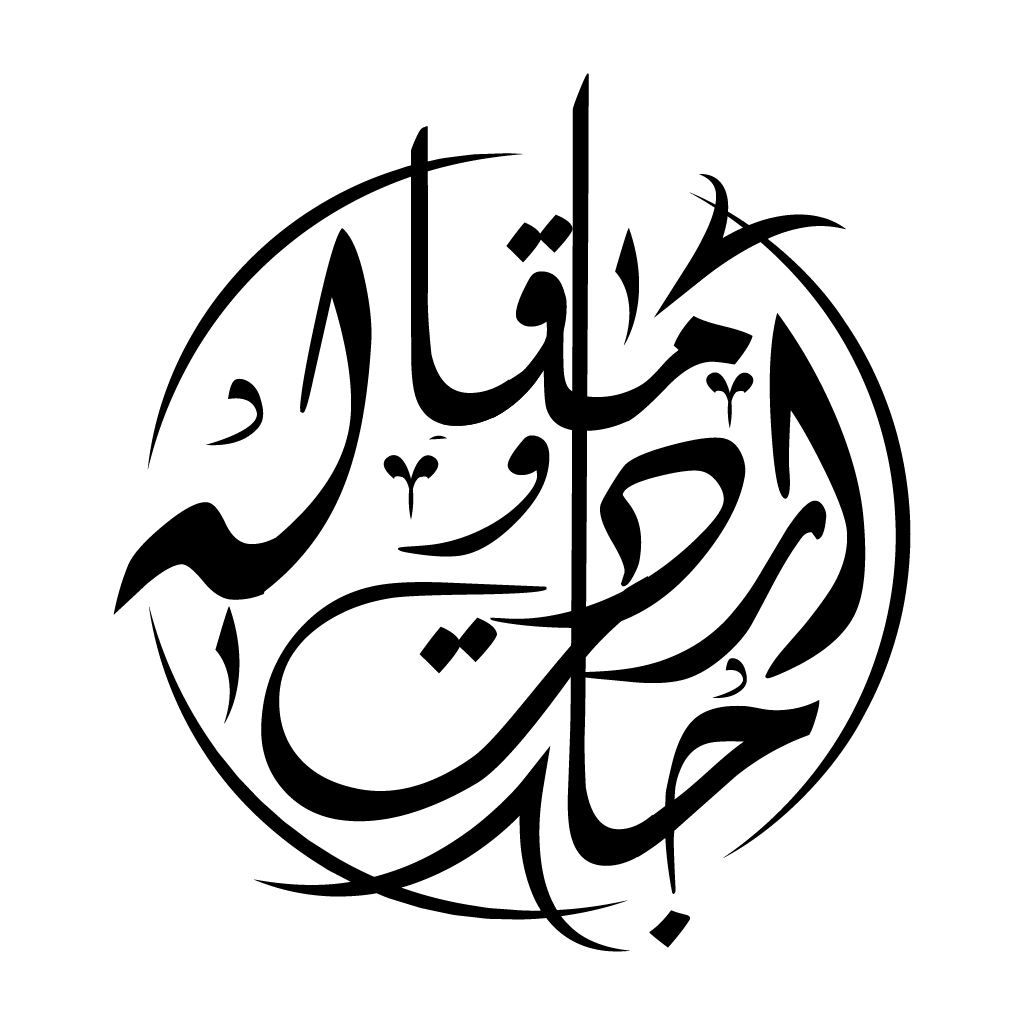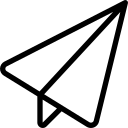اردو ادب کی تاریخ، اردو زبان کی فکری و تہذیبی ترقی کا عکاس آئینہ ہے۔ کسی بھی زبان کی ادبی تاریخ نہ صرف اس کے شعری و نثری ورثے کو محفوظ کرتی ہے بلکہ قوم کے تہذیبی و فکری رویوں کو بھی واضح کرتی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ نگاری کا آغاز انیسویں صدی میں ہوا، مگر اس نے بیسویں صدی میں باقاعدہ علمی و تحقیقی بنیاد حاصل کی۔ ابتدا میں یہ کام بیشتر طور پر جذباتی، تاثراتی اور غیر منظم انداز میں ہوا، لیکن بعد کے ادوار میں محققین نے تنقیدی اصولوں کے تحت اردو ادب کی تواریخ مرتب کیں۔
اردو ادب کی تاریخ لکھنے کی کوششیں دراصل اس وقت شروع ہوئیں جب برصغیر میں نوآبادیاتی اثرات کے تحت تحقیق و تنقید کا نیا رجحان پیدا ہوا۔ مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی، اور محمد حسین آزاد جیسے اہلِ قلم نے ادب کی تاریخی شعور کو اجاگر کیا۔
محمد حسین آزاد کی “آبِ حیات” (1880ء) کو اردو ادب کی پہلی منظم ادبی تاریخ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب تحقیقی اعتبار سے بعض کمزوریوں کی حامل ہے، تاہم اس نے اردو شاعری کی روایت کو ایک تسلسل میں پیش کیا۔ آزاد نے اسلوب میں داستانوی رنگ رکھا اور ادبی شخصیات کی سوانح کو بیانیہ انداز میں بیان کیا، جس سے کتاب کا اسلوب ادبی تو ہے مگر تحقیقی معیار سے کچھ فاصلے پر ہے۔
“آبِ حیات” اردو تاریخ نگاری کی بنیاد ہے۔ آزاد نے پانچ ادوار میں اردو شاعری کی ترقی و تنزل کا جائزہ لیا۔ ان کا مقصد محض شاعروں کی فہرست بنانا نہیں بلکہ ادبی ذوق کی تربیت بھی تھا۔
تاہم ناقدین کے نزدیک آزاد نے تاریخی ترتیب اور ماخذی تحقیق کا پورا اہتمام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ولی دکنی کے بارے میں وہ معلومات فراہم کیں جو بعد از تحقیق غلط ثابت ہوئیں۔
پروفیسر آل احمد سرور کے مطابق:
“آزاد کا کارنامہ تاریخ نویسی سے زیادہ تخلیقی بیان کا ہے۔ انہوں نے شاعری کو قصہ گوئی کے پیرائے میں پیش کیا، جس سے ادب کا ذوق تو ابھرتا ہے مگر تحقیق کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے۔”
رام بابو سکسینہ کی کتاب “تاریخِ ادبِ اردو” (1928ء) اردو تاریخ نگاری کے سائنسی منہج کی جانب پہلا قدم ہے۔ سکسینہ نے ماخذات کے حوالوں، تاریخی ترتیب اور ادبی رجحانات کے تجزیے کے ذریعے اردو ادب کی ترقی کو ایک منطقی انداز میں پیش کیا۔
ان کا کام انگریزی ادبیات کے تاریخی اسلوب سے متاثر تھا۔ انہوں نے اردو ادب کو ادوار میں تقسیم کیا: دہلوی، لکھنوی، جدید، وغیرہ۔
تاہم سکسینہ پر تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی تاریخ میں اردو کی مذہبی اور مشرقی روح کمزور پڑ گئی، کیونکہ وہ مغربی تنقید کے اصولوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔
سید محی الدین قادری زور کی “تاریخِ ادبِ اردو” (1954ء) اردو تاریخ نگاری میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ ان کی کتاب نہ صرف تاریخی ترتیب بلکہ لسانی ارتقا کے حوالے سے بھی جامع ہے۔ زور نے اردو کی ابتدا، دکنی ادب، شمالی ہند کی تحریکات، اور جدید ادبی رجحانات کا تحقیقی تجزیہ کیا۔
انہوں نے ماخذات، حوالہ جات، اور متن کی درستگی پر خاص توجہ دی۔ ان کے نزدیک:
“ادبی تاریخ محض فنکاروں کی فہرست نہیں بلکہ تہذیبی شعور کی تدوین ہے۔”
زور کی تاریخ اپنی وسعت، حوالہ جاتی صحت اور تحقیقی دیانت کے باعث اردو ادب کی سب سے معتبر تواریخ میں شمار ہوتی ہے۔
ڈاکٹر جمیل جالبی کی چار جلدوں پر مشتمل “تاریخِ ادبِ اردو“ اردو ادب کی تاریخ نگاری کا بلند ترین علمی کارنامہ ہے۔ اس میں جالبی نے اردو زبان و ادب کے ارتقا کو تاریخی، معاشرتی، تہذیبی اور فکری حوالوں سے مربوط انداز میں پیش کیا۔
ان کا منہج تقابلی اور تجزیاتی ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ہندوستانی تہذیب کے اثرات کو بھی زیرِ بحث لایا۔
پروفیسر گوپی چند نارنگ کے بقول:
“جمیل جالبی کی تاریخ اردو تہذیب کا انسائیکلوپیڈیا ہے، جس میں ہر دور کا فکری پس منظر اور ادبی میلانات جزیات کے ساتھ محفوظ ہیں۔”
جالبی کی تحریر کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو محض بیانیہ انداز میں نہیں بلکہ تنقیدی شعور کے ساتھ پیش کیا۔
ڈاکٹر حامد حسن قادری نے اردو ادب کی تاریخ کو ایک تدریسی مگر سادہ اور مستند انداز میں پیش کیا۔ ان کی کتابوں کا مقصد طالب علموں کو اردو ادب کے ارتقائی سفر سے روشناس کرانا تھا۔ ان کی تاریخ میں اختصار ہے مگر مواد کی درستی اور ترتیب قابلِ تحسین ہے۔
اردو کی منتخب ادبی تواریخ کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ اردو ادب کی تاریخ نگاری نے ایک طویل ارتقائی سفر طے کیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے تاثراتی بیانیے سے لے کر جمیل جالبی کے تنقیدی انسائیکلوپیڈیا تک، ہر دور نے اپنے فکری اور تحقیقی شعور کے مطابق تاریخ کو تعبیر کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو ادب کی نئی تاریخ عالمی تناظر میں مرتب کی جائے، جو نہ صرف اردو تہذیب کی شناخت کرے بلکہ اس کے فکری و نظریاتی جہتوں کو بھی اجاگر کرے۔